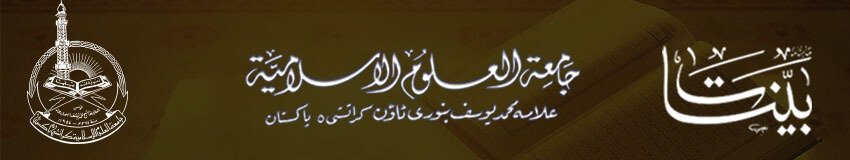
کسی بھی زبان کی انشاء سیکھنا سکھانا انتہائی مشکل کام ہے، پھر خصوصاً عربی انشاء ایک صبر آزما اور جفاکشی والا عمل ہے؛ کیونکہ نفس کو کتابت پر آمادہ کرنا ایک بھاری بوجھ ہے ؛ ا س کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کے بولنے کا انداز الگ اور لکھنے کا طرز الگ ہوتاہے، ایک بات بولنے میں ایک طرز کی ہوتی ہے، اگراسی طرز کوبعینہ باقی رکھ کر لکھا جائے تو عموماً وہ تحریر عمدہ شمار نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس کے اسلوب کو بدلنا ناگزیر ہوتا ہے، عربی انشاء پڑھانے اور سکھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اگر انہیں اپنایا جائے تو انشاء کی تعلیم کا رگر ہوسکتی ہے، ورنہ معلم اور متعلم دونوں کا وقت خدا نخواستہ ضائع ہوجاتاہے۔
ہمارے نظامِ تعلیم کا المیہ یہ ہے کہ یہاں عربی انشاء پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، اور انشاء پڑھانے والا استاذ کوئی فنی استاذ شمار نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ پھر استاذ بھی اس فن میں اپنی توانائی صرف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن اگر اس فن کو بحیثیت فن اور علم پڑھا اور پڑھایا جائے تو قوی اُمید ہے کہ اس سے مطلوبہ فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم باتیں جن کا دورانِ تدریس تجربہ ہوا سپردِ قرطاس کی جاتی ہیں، شاید کسی انشاء سیکھنے سکھانے والے کو اس سے فائدہ ہوجائے۔
1- فنِ انشاء میں مذکورہ کمزوریاں رہ جانے کی وجہ سے ذمہ داران حضرات اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ انشاء کا سبق کسی ایسے ماہر استاذ کے سپرد کیا جائے جو اس فن میں مہارت یا کم از کم ذوق رکھتا ہو، اگر ایسا کوئی نہ ملے تو پھر وہ استاذ پڑھانے کےلیےمناسب ہے جو صرف ونحو میں مہارت رکھتاہو اوروہ عام طور پر نحو کی بنیادی کتابیں پڑھانے والاہو۔
2- معلم الإنشاء کی کتاب شروع کرنے سے پہلے استاذ طلبہ کو وہ الفاظ و معانی یاد کرائے جو کتاب کے آخر میں بطور معاون کے لکھے گئے ہیں۔ یہ الفاظ و معانی اس ترتیب سے یاد کرائے کہ روزانہ کے سبق کے ساتھ ایک صفحہ یا د کرنے کےلیے دیا کرے، ایک مرتبہ تمام الفاظ معانی ختم ہونے کے بعد دوسری مرتبہ دو دو یا تین تین صفحات یاد کرنے کےلیے دے، اس سے تمرینات حل کرنے میں فائدہ ہوگا اور ذخیرۂ الفاظ بھی جمع ہوگا۔
3- سال کے شروع سےتمام طلبہ کو ذاتی قاموس ( ڈکشنری) رکھنے کا پابند بنایا جائے، تاکہ دورانِ سبق اس کی طرف مراجعت کرسکے۔ ایک عربی سے اردو والا قاموس، دوسرا اُردو سے عربی والا قاموس ضرور ہر طالب علم اپنے پاس رکھے، اور استاذ خودبھی دورانِ مطالعہ زیادہ اعتماد کسی بھی شرح پر کرنے کے بجائے قاموس رکھے اور اس پر ہی اعتماد کیا کرے۔
4- استاذ معلم الانشاء کا سبق خود بالاستیعاب تقریر کے انداز میں ہر گز نہ پڑھائے، جیسے دوسری کتابوں کی تقریریں کی جاتی ہیں، بلکہ روزانہ کا سبق طلبہ ہی سے اپنی موجودگی میں حل کرائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوکہ طلبہ چونکہ الفاظ کے معانی یاد کرچکے ہوں گے (جیسے کہ پہلی ہدایت میں بیان ہوا)، صرف اسے ترتیب دینا باقی ہوگا، اور ہر طالب علم سے باری باری پہلےاسماء مفردات پوچھے جائیں، پھر افعال اور اس کے بعد اسی ترتیب پر جملے کی بناوٹ مکمل کیا کریں، اس طرزِ تدریس میں اگرچہ وقت زیادہ صرف ہوگا، مگر ضائع نہ ہوگا، اس سے طلبہ از خود اردو سے عربی اور عربی سے اردو ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔
5- روزانہ کی تمرین طلبہ سے حل کرانے کے بعد اسے لکھوانے کا اہتمام کرے، اور پھر اگلے دن لکھی ہوئی تمارین کی تصحیح کر لیا کریں، تمرین حل کرنے میں ہر گز کسی کے ساتھ نرمی نہ کی جائے، تاکہ لکھنے کی عادت پڑے، اور انہیں بقدرِ استطاعت عربی خط میں عبارات لکھنے کی تلقین کرے؛ تاکہ تحریر کی کمزوریاں اور اغلاط بھی درست ہوسکیں، اور تمام تمرینات تصحیح کے بعد چھٹی کے دن الگ کاپی میں نقل کرکے لکھوائیں ۔
6- ہماری رائے میں انشاء کا گھنٹہ دوسرے گھنٹوں کی بنسبت دس پندرہ منٹ لمبا ہونا چاہیے، تاکہ انشاء پڑھانے والا استاذروزانہ کے حساب سے کچھ وقت اسی گھنٹے میں کچھ وقت نکال کر عربی تکلم کے لیے خاص کردے، اس سے طلبہ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔
7- استاذ کم از کم ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ کوئی قصہ یا کہانی اردویا عربی میں سنا کر اس کا عربی یا اردو میں ترجمہ کرایا کرے، اور اس میں نئے الفاظ نکال کر جملے بنوائے، اس سے ان کو عربی میں گفتگو کا موقع مل سکے گا۔
8- پہلی سہ ماہی گزرنے کے بعد قصص کا سلسلہ ختم کرکے اس کی جگہ نصابی کتابوں میں سے ہر کتاب سے ایک سوال بنا کر عربی میں لکھوایا جائے، اس کی وجہ سے کتابوں کے سبق میں پختگی پیدا ہوگی اورعربی تحریر کی مشق خوب سے خوب تر ہوگی۔
9-استاذ عربی بول چال وتحریر کے تمام موضوعات پر گہری نظر رکھے، بالخصوص وہ موضوعات جو معلم الانشاء کی کتاب میں نہ ملیں، جیسے گھڑی کا وقت، اَرقام واَعداد کا استعمال، اس کو بھی پڑھانے کا اہتمام کرے، اس کے لیے دیگر کتابوں سے مدد لی جاسکتی ہے، مثلاً : الطریقۃ العصريۃ (الجزء الأول) سے الساعۃ کا سبق ایک دن پڑھائے، اَرقام واَعداد کا سبق الطریقۃ العصريۃ (الجزء الثاني) سے چند دن پڑھائے، الطریقۃ العصريۃ کا دوسراحصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، استاذ اگر مناسب سمجھے تو اس سے وقتاً فوقتاً سبق کی شکل میں پڑھالیا کرے۔
10-حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے نحومیر یا علم النحو کے طریقۂ تدریس کے ذیل میں تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے، جس کا ایک اقتباس یہاں نقل کیا جاتاہے، چنانچہ فرماتےہیں:
’’اساتذہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علومِ اسلامیہ کی تحصیل کےلیے ٹھیک ٹھیک فہم، اس کا مکمل اجراء اور اس کے قواعد کا صحیح استعمال ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتاہے، لہٰذا نحو کی تعلیم پر آنے والےہر علم وفن کی تحصیل موقوف ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور رہ جائےتو دورہ حدیث تک کی پوری تعلیم کمزور، بے اثر اور بےثبات ہوجاتی ہے، اس لیے نحو کے استعمال کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کےلیے مندرجہ ذیل امور کی رعایت ناگزیر اور لازمی ہے:
1: نحو کی تعلیم میں اصل مقصد کتاب کی عبارت یاد کرانا نہیں، بلکہ اس میں بیان کردہ قواعد ومسائل کا طالب علم کو اس طرح ذہن نشین کرانا ہے کہ متعلقہ موقع پر طالب علم کو وہ قاعدہ یا مسئلہ یاد آجائے۔
2: زیرِ درس کتاب میں عموماً کسی اصطلاح یا قاعدے کی تشریح کےلیے صرف ایک مثال پر اکتفا کیا گیا ہوتا ہے، لیکن استاذ کےلیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر اصطلاح اور قاعدے کی تشریح کےلیے طلبہ کے سامنےاز خود بہت سی مثالیں بیان کرےاور بہتر یہ ہے کہ یہ مثالیں عام گفتگو کے علاوہ قرآن کریم سے بھی اخذ کی جائیں، تاکہ قرآن کریم سے مناسبت پیدا ہوتی جائے، اس غرض کےلیے استاذ کو چاہیے کہ ’’مفتاح القرآن‘‘ کو مستقل مطالعہ میں رکھے۔
3: خود بہت سی مثالیں دینے کے بعد طلبہ سے مثالیں بنوانا اور مختلف مثالیں بول کر طلبہ سے ان کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے، یہ کام زبانی بھی ہونا چاہیے اور تحریری بھی۔
4: طالب علم جب بھی کوئی غلط جملہ بولےیا غلط پڑھے، اس کو فوراً ٹوک کر جملہ درست کرایا جائے، عام طور سے طلبہ میں مضاف پر الف لام داخل کرنے، موصوف صفت اور مبتدا خبر میں مطابقت نہ کرنے وغیرہ کی غلطیاں شروع سے جڑ پکڑجاتی ہیں، ان غلطیوں کوکسی بھی قیمت پرگوارا نہ کیا جائے، بلکہ طالب علم سے اصلاح کرائی جائے، تاکہ شروع ہی سےان غلطیوں سے احتراز کی عادت پڑجائے۔
5: طلبہ کو ہر روز یا کم از کم تیسرے دن کوئی نہ کوئی مشق ضرور دی جائے، اور مشقوں کا طریقہ وضع کرنے کے لیے استاذ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ’’عربی کا معلم‘‘، ’’معلم الإنشاء‘‘ اور ’’النحو الواضح للابتدائیۃ ‘‘کو اپنے مطالعے میں رکھے، اور جو بحث پڑھائی گئی ہے، اس کے متعلق ان کتابوں میں دی گئی مشقوں میں سے طلبہ کی ذہنی سطح کا لحاظ رکھتے ہوئے مشقیں منتخب کرکے طلبہ کو ان کے تحریری جواب کا پابند بنائے۔‘‘ (درسِ نظامی کی کتابیں کیسے پڑھیں اور پڑھائیں؟ص: ۱۱ تا ۱۴)
11- علاماتِ وقف و فواصل (قواعدِ املاء) اور ہمزہ کی درست کتابت کا خوب اہتمام کریں، اس کے لیے الطریقۃ العصريۃ (الجزء الأول) کا آخری سبق پڑھایا جائے، اس میں علاماتِ ترقیم انتہائی آسان انداز میں تحریر کیے گئے ہیں، اسے پڑھانے کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی عملی تطبیق واجراء کراتے رہیں، اس سلسلہ میں ہمزہ کے قواعد انتہائی اہم ہیں، جو مختلف کتبِ انشاء وتعبیر سے دیکھ کر پڑھائے جائیں۔
1- عربی زبان کی تعلیم کےلیے رائج جدید کتب اپنے مطالعہ میں رکھے؛ تاکہ استاذ کی معلومات اور ذخیرۂ الفاظ میں مسلسل اضافہ ہو، اس میں ہمارے استاذ (شیخ موسیٰ العراقی) کی ایک اہم کتاب ’’لغۃ المسلم‘‘ ہے جو روزمرہ عربی کے جملے اور عبارات سکھانے کےلیے عمدہ ترین کتاب ہے، ان کی دوسری کتاب ’’العربیۃ المعاصرۃ ‘‘ہے جو درحقیقت ’’لغۃ المسلم‘‘ کا دوسرا حصہ ہے، تاہم اس وقت ’’لغۃ المسلم‘‘ کے مختلف نئے نسخے مختلف ناموں سے چھپے ہیں، اس کے علاوہ مفردات کےلیے ’’القاموس المصور ‘‘ کے نام سے اچھا کام ہوا ہے، وہ بھی زیرِ مطالعہ رہے۔
2- استاذ خود کتاب فہمی کے ساتھ ساتھ دیگر عربی ادب کے قدیم وجدید شہ پارے مطالعہ میں رکھے، بطور خاص چند کتابوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں: مصر کے مشہور ادیب دکتور علی طنطاوی کی اکثر کتب مطالعہ میں رکھے، جیسے : مقالات في کلمات، نور وہدایۃ، فصول إسلامیۃ، فصول في الثقافۃ والأدب وغیرہ، احمد امین کی کتب جیسے: حیاتي، عبد الرحمٰن رافت الباشا کی صور من حیاۃ الصحابۃؓ و صور من حیاۃ التابعینؒ، منفلوطی کی کتب مطالعہ میں رکھیں، جیسے: نظرات، عبرات، علامہ ندویؒ کی کتب بطور خاص دیکھے، ان میں سے ’’نظرات في الأدب، ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمین‘‘مطالعہ میں رکھے، جبکہ ذخیرۂ الفاظ کے لیے ہمذانی کی ’’الألفاظ الکتابیۃ‘‘ اورثعالبی کی ’’فقہ اللغۃ‘‘ کا مطالعہ کرے۔ ذخیرۂ الفاظ کےلیے ’’الألفاظ الکتابیۃ للہمذاني‘‘ دیکھے، اسی طرح فقہ اللغۃ للثعالبي اس سلسلے میں ایک عمدہ کتاب ہے۔
3- استاذ جدید کلمات کے معانی جاننے کے لیے معاجم اور قوامیس کا استعمال ضرورکرے، اور طلبہ کو بھی قاموس استعمال کرنے کا پابند بنایا جائے، اور ان کو قاموس سے اسماء وافعال تلاش کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے، قوامیس میں بہتر یہ ہے کہ عربی سے عربی قاموس کا استعمال کیا جائے؛ کیونکہ اس سے عربی کا ترجمہ عربی سے کرنے اور سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہوگا، اس کےلیے عمدہ ’’قاموس المعجم الوسیط‘‘ ہے جو عربی سے عربی کا ترجمہ کرتا ہے، یا عربی سے اردو قاموس استعمال میں رکھے، اس کے علاوہ ’’القاموس الوحید‘‘ اردو زبان میں عربی کا ایک عظیم معجم ہے جس میں لاکھوں عربی الفاظ کے معانی دئیے گئے ہیں۔
4- استاذ صاحب پہلے سےسبق کا گہرا مطالعہ کرے، اور اس کے نئے کلمات اور جملوں کو خوب ذہن نشین کرلے، عبارت کی پیچیدگی کی وجہ سے کہیں مشکل پیش آئے تو اردو شرح سے مدد لی جاسکتی ہے، اس سلسلہ میں کئی علماء نے نفحۃ العرب کی خدمت کی ہے، ان میں سے عمدہ عربی حاشیہ جو خود مصنفِ کتاب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور کتاب کے ساتھ چھپاہوا ہے، اس سے مشکل مقامات آسان ہوجاتے ہیں، اس کے علاوہ اردو میں کئی علماء نے اس کی شروح لکھی ہیں، ان سے بقدرِ ضرورت مدد لی جاسکتی ہے، بشرطیکہ اس پر کلی طور پر انحصار واتکال نہ کرلیا جائے، چنانچہ اس کی جدید شرح جو مولانا مصلح الدین قاسمی صاحب (استاذ دارالعلوم دیوبند)نے تصنیف کی ہے، اس سے کتاب کے مشکل مقامات حل ہوجاتے ہیں۔
عموماً عربی کتابوں کی تدریس کا مقصد یہ ہوتاہے کہ ان سے عربی الفاظ وتعبیرات اخذ کرکے ان سے اپنے ذخیرۂ الفاظ وتعبیرات میں اضافہ کیا جائے، اوران سے کلا م کا اسلوب اخذ کرلیا جائے، مذکورہ کتاب پہلے مقصد (ذخیرۂ الفاظ وتعبیرات) میں بڑی حدتک معاون ہے، لیکن دوسرے مقصد (اسلوب اخذ کرنے) میں زیادہ معاون نہیں۔ نفحۃ العرب کی نثر ادبِ عربی کے قدیم اُسلوب پر ہے؛ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب احادیث وسیر اور عربی ادب کی قدیم کتابوں کو سمجھنے میں ضرور معاون ہے، مگر جدید عربی ادب میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دیتی، تاہم یہاں اس کی تدریس سے متعلق چند باتیں بیان کی جاتی ہیں:
ہر نئے سبق میں آنے والے مفردات لکھواکر یاد کرائے جائیں، اور جس طرح عربی الفاظ کے متبادل اردو الفاظ سنے جائیں، اسی طرح اردو معانی کو پوچھ کر ان کے عربی الفاظ کو بھی سننے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ انہیں جہاں عربی الفاظ کے اردو متبادل معلوم ہوں گے، وہیں اردو مفاہیم کے لیے عربی الفاظ بھی یاد ہوں گے؛ کیونکہ بولنے اور لکھنے کےلیے اردو کے متبادل عربی الفاظ کا بروقت یاد آنا نہایت ضروری ہے؛ اس کے بغیر نہ آپ عربی لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔
ہندوستان کے مشہور ومعروف ادیب صاحبِ القاموس الوحید اورمصنفِ کتبِ کثیرہ حضرت مولانا وحید الزمان کیرانویؒ لکھتے ہیں: ’’نیز عربی الفاظ کے معانی جیسے اردو میں یاد کرائے جائیں، اسی طرح اردو الفاظ کے عربی معنی بھی یاد کرائے جائیں، اس طرح زبان کے دونوں رخ سامنے رہیں گے اور تکلم وانشاء میں سہولت رہے گی۔‘‘ (شرح القراءۃ الواضحۃ: ۱ / ۴)
تمام طلبہ سے روزانہ صحیح تلفظ اور خالص عربی لب ولہجے میں سبق کی جہری قراءت کرائی جائے، تعداد زیادہ ہوتو باری مقرر کرلی جائے، یا تھوڑی تھوڑی عبارت کئی طلبہ سے پڑھوائی جائے، مگرکسی کو عبارت پڑھنے سے مستثنیٰ نہ رکھاجائے، جو عبارت طلبہ کو استاذ کے سامنےپڑھنی ہے، طلبہ پہلے اسےکم از کم پانچ بار خارج میں صحیح تلفظ اور درست لہجے میں پڑھ کر آئیں، طلبہ کو یہ بھی تاکید کی جائے کہ عبارت سمجھ کر اور ذہن کوحاضر رکھ کر پڑھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ الفاظ وتعبیرات ذہن نشین ہوسکیں۔
ایک کتاب کو باربار پڑھنے کے کئی فوائد ہیں، جیسا کہ کسی نے کہاہےکہ: قراءَۃُ کتابٍ ثلاثَ مراتٍ خیرٌ من قراءۃِ ثلاثۃِ کُتُبٍ (ایک کتاب کو تین بار پڑھنا تین کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے)، اس کے علاوہ کثرتِ قراءت کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند یہاں قارئین کے فائدے کےلیے درج کیے جاتے ہیں:
1- پہلا فائدہ: ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہر زبان کا اپنا لب ولہجہ ہوتا ہے، اس لہجے کو سیکھے بغیر اس زبان پر کما حقہ دسترس حاصل نہیں ہوسکتی، یہی حال عربی زبان کا بھی ہے، چنانچہ طالب علم جب عربی عبارت کی عربی لب ولہجے میں قراءت کرے گا، تورفتہ رفتہ وہ عربی لہجہ سیکھ جائے گا۔
2 - دوسرا فائدہ: عربی قراءت سے زبان عربی نطق کی عادی بن جائے گی، اور اس سے عربی نطق میں سہولت رہے گی، بسا اوقات ہوتایہ ہے کہ آدمی جب بولنے کا ارادہ کرتاہے تو ذہن میں صحیح لفظ آتاہے، مگر بولتے ہوئے کچھ کا کچھ ہوجاتاہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان عربی الفاظ کی ادائیگی کی عادی نہیں ہوتی، لہٰذا کثرتِ قراءت سے زبان کو عربی نطق کا عادی بنانا ضروری ہے۔
3- تیسرا فائدہ: یہ فائدہ سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ کثرتِ قراءت سے طالب علم کو مفردات کے ساتھ تعبیرات کا بھی بڑا حصہ یاد ہوجاتا ہے، اور لکھنے بولنے میں سب سے بنیادی کردار ذخیرۂ الفاظ وتعبیرات کا ہے۔
(الف) کتاب میں صرف نئی آنے والی لغات لکھوائی جائیں، اورانہیں یاد کرانے کے بعد سوالات بھی کیے جائیں، تاکہ آئندہ کےلیے پرانی لغات یاد رہیں، اور آگے لغات لکھوانے اور یاد کرانے کا کام بھی مختصر رہے گا۔
(ب) نئے مفرد الفاظ کی جمع اور جمع کی مفرد بھی بتائی جائے، اور افعال میں ہرفعل کا باب بھی بتادیا جائے، نیز فعل کا وہ معنی بتایا جائے جو وہاں مراد ہو، جو معنی مراد نہ ہووہ نہ لکھوایا جائے، تاکہ طالب علم پر اضافی بوجھ نہ پڑے، اور ’’طلب الکل فوت الکل‘‘ کا سبب نہ بنے۔
(ج) افعال کے صلات لکھوائے جائیں، جو افعال صلات کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان کے صلات لکھوانے اور یاد کرانے کا اس طرح التزام کیا جائے کہ جب طالب علم کے ذہن میں فعل آئے تو اپنے صلہ کے ساتھ آئے، بعض افعال کا استعمال صلات کے ساتھ ہوتاہے، بعض کا بغیر صلات کے، ہر ہر فعل کے ساتھ یہ بتادیا جائے کہ اس کا استعمال صلہ کے ساتھ یا بغیر صلہ کے ہے، صلہ کی پہچان انتہائی ضروری ہے، کیونکہ صلہ بدلنے سے معنی کچھ کا کچھ ہوجاتا ہے۔ مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
’’افعال کے ساتھ جہاں جو صلات استعمال ہوں، ان کو افعال کا ایسا جز لازم تصور کرایا جائے کہ جب طالب علم اس فعل کو زبان یا نوکِ قلم پر لائے تو معاً اس کا صلہ بھی ذہن میں آجائے۔‘‘ (دلیل القراء الواضحۃ: ۱/۴)
فنِ انشاء کی طرح ترجمہ بھی ایک مستقل فن ہے، ان کتابوں سے جہاں طلبہ کو انشاء وادب سکھائی جاتی ہے، وہاں انہیں ان میں بتدریج معیاری ترجمہ کا سلیقہ بھی پیدا کرنا ہے، مولانا وحید الزمان کیرانویؒ نے تحریر فرمایا ہے:’’عام طور پر ہمارے مدارس میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے، اس میں اس زبان کے قواعد ملحوظ رکھے جاتے ہیں جس سے ترجمہ کیا جارہا ہے، حالانکہ ترجمہ کا مسلم اصول اس کے برعکس ہے، یعنی جس زبان میں ترجمہ کیا جائے اس کے قواعد ملحوظ رکھے جاتے ہیں، اس صورت میں ترجمہ سلیس اور شگفتہ ہوجاتا ہے۔‘‘ (شرح نفحۃ الادب : ۳)
عربی سے اردو ترجمہ کرنے میں اُردو قواعد کی رعایت رکھنے کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں:
1- عربی میں فعل عموماً پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتاہے، پھر مفعول اور متعلقات وغیرہ آتے ہیں، جب کہ اردو میں سب سے پہلے فاعل، اس کے بعد مفعول اور متعلقات وغیرہ اس کے بعد آخر میں فعل آتاہے، جیسے عربی میں آپ کہیں گے: رکب حامد الدراجۃ، اور اردومیں آپ کہیں گے: حامد سائیکل پر سوار ہوا۔ عربی جملے میں فعل شروع میں ہے، جبکہ اردو جملے میں بالکل اخیر میں ہے، اگر یہاں تحت اللفظ ترجمہ کیا جائے تو اردو کے اسلوب کے خلاف ہوجائےگا۔
2- اسی طرح جب ہم افعال کا ترجمہ کرتے ہیں تو عربی فعل کا اردو متبادل لا تے ہیں، مگر عربی افعال کے جو صلات ہیں ہم ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں ان کے متبادل نہیں لاتے، بلکہ اردو کا لحاظ کرتے ہیں، اگر وہ اردو میں وہ فعل صلہ نہیں چاہتا تو نہیں لاتے، مثلاً ہم عربی میں کہتے ہیں:’’ذہب حامدٌ إلی السوق‘‘ اور اردو میں کہتے ہیں: ’’حامد بازار گیا ‘‘ اردوفعل ’’ گیا‘‘ صلہ نہیں چاہتا، اس لیے ہم اس کا لحاظ کرتے ہوئے صلہ نہیں لائے، اور اگر اردو کا فعل صلہ چاہتا ہے تو جو صلہ وہ چاہتا ہے وہی لاتے ہیں، عربی والے کا اردو متبادل نہیں لاتے، مثلاً : ہم عربی میں کہتے ہیں: ’’شَکَوْتُ إلی الأستاذ‘‘ مگر اردو میں ہم ’’إلی‘‘ کا متبادل’’تک‘‘ لانے کے بجائے ’’سے‘‘ استعمال کرتے ہیں، چنانچہ ہم کہتے ہیں: ’’میں نے استاذ سے شکایت کی‘‘ اسی طرح عربی میں ہم کہتے ہیں: ’’تَمَکَّنَ حَامدٌ مِنَ التدريس‘‘ مگر اردو میں ’’مِن ‘‘ کا متبادل ’’سے‘‘ لانے کے بجائے ’’پر‘‘ لاتے ہیں اور کہتے ہیں: ’’حامد تدریس پر قادر ہوگیا‘‘ اس لیے کہ اردو فعل قادر ہونا ’’پر‘‘ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔
3- بعض مفاہیم عربی میں مجہول افعال سے ادا کیے جاتے ہیں، مگر اردو میں کئی مواقع پر فعل لازم معروف استعمال ہوتا ہے، مثلاً: عربی میں ہم کہتے ہیں: ’’فُتِحَ البابُ، اُغْلِقَ الدکانُ، وُضِعَ الأسَاسُ، بِيْعَتِ الدارُ، اُغْمِيَ علیہ‘‘ یہ سارے افعال عربی میں مجہول ہیں، مگر اردو میں ان مواقع پر فعل مجہول کے بجائےفعل لازم استعمال ہوتا ہے، چنانچہ ہم کہتے ہیں: ’’دروازہ کھلا، دوکان بند ہوگئی، بنیاد پڑی، گھر فروخت ہوگیا، وہ بے ہوش ہوگیا‘‘ ان مواقع پر اگر ہم اردو میں فعل لازم کے بجائے فعل مجہول استعمال کریں گے تو اردو بہت سی جگہوں اور محاوروں کی رو سے صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا جہاں ایسا موقع ہو وہاں ترجمہ عمل لازم سے کیا جائے، اور طلبہ کو بتایا جائے کہ یہاں عربی کے محاورے میں فعل مجہول استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی ان مواقع پر عربی میں فعل مجہول استعمال کریں گے، اور اردو میں فعل لازم ہوتا ہے، لہٰذا اردو کا لحاظ کرتے ہوئے ہم بھی لازم استعمال کریں گے، نہ عربی کو اردو پر مسلط کریں گے اور نہ اردو کو عربی پر۔
4- اسی طرح آج کل سبب کو عربی میں فعل متعدی کا فاعل اوراس کے نتیجہ کو مفعول بہ بناکر بکثرت استعمال کرتے ہیں، مگر اردومحاورے کی رعایت کرتے ہوئے ہم بہت سی دفعہ سبب کو فاعل اور وجہ بنا کر ہی ترجمہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عربی کے فعل متعدی کو اردو میں لازم بنانا پڑتا ہے، جیسے: ’’الازدحامُ اَوْقَفَ السَّيَّارَاتِ، غِیَابُ الولدِ عن البيت اَقْلَقَ الوالدۃَ، جَرَسُ الہاتفِ أزعَجَ المريضَ‘‘ ہم اردو میں ان مفاہیم کو عموماً اس طرح ادا کرتے ہیں: ازدحام کی وجہ سے گاڑیاں رک گئیں، گھر میں بچے کی عدم موجودگی سے ماں پریشان ہوگئی، موبائل کی گھنٹی سے مریض کو اُلجھن ہونے لگی۔ اس کے برعکس اگر ان کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اردو کے اسلوب اور قواعد کے خلاف لازم آئے گا، جیسے کہاجائے: رش نے گاڑیاں روک دیں، بچے کے گھر سے غائب ہونے نے ماں کو پریشان کردیا، موبائل کی گھنٹی نے مریض کو اُلجھن میں ڈال دیا، لہٰذا ترجمہ کا صحیح اسلوب یہ ہے کہ سبب اگرچہ یہاں فاعل اور نتیجہ مفعول بہ ہے، مگر ترجمہ میں اس کے برخلاف کرنا پڑے گا، جیسا کہ تفصیل سے ذکر ہوا۔
5- اردو کے ظرف کو عربی میں بسا اوقات فعل کا فاصل بنا کر استعمال کرتے ہیں، ہم اردو ترجمہ میں اسے ظرف بنا کر ترجمہ کرتے ہیں جیسے: ’’شَہِدَتْ فلسطینُ حربا دامیۃ في ھٰذا الشھر، قال: ذٰلک تصریحٌ صادرٌ عن القنصلیۃ‘‘ پہلے جملے میں ’’فلسطین‘‘، ’’شھدت‘‘ فعل کا فاعل ہے، اور دوسرے جملہ میں ’’تصریح‘‘، ’’قال‘‘ فعل کا فاعل ہے، مگر ترجمہ کرتے وقت ہم اسے ظرف بنا دیتے ہیں، چنانچہ اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے: ’’فلسطین میں اس ماہ خونریز جنگ ہوئی، سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا۔‘‘ یہ ترجمہ میں اردو محاورے اور استعمال کی رعایت کے چندنمونے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ترجمہ میں زبانِ مترجم الیہ کی رعایت ضروری ہے، اگر ایسا نہ کیاجائےتو ترجمہ اردو کے استعمال کے لحاظ سے غلط ہو جائے گا۔
6- نفحۃ العرب کی عبارت کافی پیچیدہ اورمشکل ہے، اس لیے جہاں طلبہ کےلیے سلیس اردو ترجمہ مشکل ہورہاہو، وہاں پہلے لفظی ترجمہ سمجھایا جائے، پھر سلیس ترجمہ بتادیا جائے، اور اگر اس کےبعد بھی طلبہ کوسلیس ترجمہ میں دشواری ہوتو پھر جہاں جہاں دشواری ہو، وہاں لفظی ترجمہ ہی کرالیا جائے۔
7- نفحۃ العرب کی نثر عام طلبہ کی سطح سے بلند ہے، پھر انشاء و ادب کی کتابوں میں جو منہجیّت اور تدریج ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ نثر کا معیار بلند ہوتا ہے، وہ بھی یہاں نہیں ہے، قدیم ادبی کتابوں سے مختلف اقتباسات اور تراشے تدریج کالحاظ کیے بغیر جمع کردیے گئے ہیں، ان اسباب کی وجہ سے کتاب طلبہ کو مشکل معلوم ہوتی ہے، پھر نصاب بھی زیادہ ہے، لہٰذا استاذ کو چاہیے کہ اسے زیادہ وقت دے، کتاب توجہ سے پڑھائے اور اسباق کو سننے کا خصوصی اہتمام کرے، کتاب میں ذکر کردہ حکا یتیں اور ان میں ذکر کردہ شخصیات بھی نامانوس ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی طلبہ کو کتاب سے وحشت ہوتی ہے۔ استاذ کو چاہیے کہ سبق شروع کرنے سے پہلےاس میں ذکر کردہ حکایت یا لطیفے کو پہلے اپنی زبان میں بیان کردے، پھر سبق پڑھائے، ان شا اللہ! اس سے اُنسیت بڑھے گی اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ (جاری ہے)