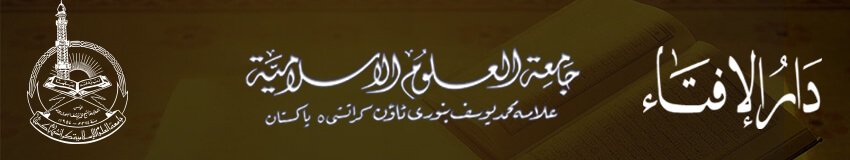
حدیث میں ہے کہ : ”اے ابن آدم! میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اور تیرے چہرے پر پردہ ڈالا تاکہ تو رحم سے متنفر نہ ہو جائے، اور میں نے تیرا چہرہ تیری ماں کی پیٹھ کی طرف کر دیا تاکہ کھانے کی بو تجھے تنگ نہ کرے، تمہارے دائیں طرف تکیہ لگایا اور بائیں طرف بھی تکیہ لگایا ، تمہارے دائیں طرف کا تکیہ جگر اور بائیں طرف کا تکیہ تلی کو بنایا، اور میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں کھڑا ہونا اور بیٹھنا سکھایا ، یہ کام میرے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ پس جب تمہارا وقت پورا ہو گیا اور میں نے رحموں کے ذمہ دار فرشتے کو وحی کی کہ تجھے نکالے، تو اس نے تجھے اپنے بازو کے ایک پر پہ اٹھا کر نکالا، تیرے پاس کاٹنے کو کوئی دانت نہیں تھے، نہ پکڑنے کے قابل ہاتھ تھے، نہ چلنے کے لائق پاؤں تھے، لہذا میں نے تیرے لیے تیری والدہ کے سینے میں دو رگیں چلا دیں ،جن کے اندر سردیوں میں خالص اور گرم دودھ جب کہ گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ جاری کیا، اور میں نے تیری محبت تیرے والدین کے دلوں میں ڈالی تو وہ اس وقت تک سیر نہ ہوتے تھے جب تک تو سیر نہ ہو جائے، وہ اس وقت تک نہ سوتے جب تک تو نہ سو جائے، پس جب تیری کمر مضبوط ہو گئی اور تیرا زور بازو انتہا کو پہنچ گیا تو توں نے تنہائی میں گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور تجھے مجھ سے شرم نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود اگر تو نے مجھے پکارا تو میں نے تیری پکار کو سنا، اور اگر توں نے مجھ سے مانگا تو میں نے تجھے عطا کیا ، اور اگر تو نے توبہ کی تو میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا۔“
مذکورہ بالا روایت ، حدیث قدسی کے طور پر پیش کی جاتی ہے ، کیا یہ بات صحیح ہے ؟
سوال میں مذکور روایت بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں کافی تلاش کے باوجود کسی مستند کتُبِ حدیث میں سے نہیں مل سکی،البتہ اس سے ملتی جلتی ایک روایت (حلية الأولياء) میں ملتی ہے،ذیل میں وہ پوری سند کے ساتھ ذکر کی جا تی ہے، لیکن یہ روایت بھی اسرائیلیات میں سے ہے، اور مذکورہ روایت پر تلاش کے باوجود ہمیں کسی محدث کا کلام نہیں مل سکا، لہذا اس روایت کا شمار اُن اسرائیلی روایات میں سے ہوگا کہ جن کے بارے میں نہ ہم تصدیق کرسکتے ہیں اور نہ تکذیب کرسکتےہیں، اور نہ ہی اس سے عمل کا کوئی تعلق ہے، البتہ اسرائیلی ہونے کی تعیین کرکے بیان کرنے کی گنجائش ہوگی۔
اور اسرائیلی روایات سے متعلق تفصیلی حکم یہ ہے کہ ہمارے عرف میں جس واقعے کا ذکر یا اس کے کسی حصے کا ذکر قرآنِ مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اسے اسرائیلی روایت نہیں کہاجاتا، بلکہ وہ ہمارے دینی مآخذ شمار ہوتے ہیں۔ جب کہ وہ روایات جن کا ذکر بعینہ یا ان کے کسی حصے کا ذکر قرآنِ مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو، انہیں اسرائیلی روایت کہا جاتاہے۔
چوں کہ یہود و نصاریٰ اپنی کتابوں میں تحریف کرچکے ہیں؛ اس لیے اُن روایات پر مکمل اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے جو صرف ان کی کتابوں میں موجود ہوں، چنانچہ ان روایات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی ایسی بات ہو جس کی تصدیق ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہو تو ہم ایسی روایات کی تصدیق کریں گے اور ان روایات کا بیان کرنا جائز بھی ہوگا، اور جن میں ایسی باتیں ہوں جس کی تصدیق تو ہمیں قرآن و حدیث میں نہ ملتی ہو، لیکن وہ قرآن و حدیث (یعنی شریعت) کے کسی مسلمہ اصول سے ٹکراتی بھی نہ ہوں تو ایسی روایات کا حکم یہ ہے کہ ہم نہ تو ان روایات کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی تکذیب کریں گے، البتہ ان روایات کو بیان کرنے کی گنجائش ہے، اور جن روایات میں ایسی باتیں ہوں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں تو ہم ان کی تکذیب کریں گے، اور ایسی روایات کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔
ان روایات کی پہچان ،محدثینِ کرام اور ائمہ جرح و تعدیل کا کام ہے، جو لوگ حدیث کے فن میں مہارت رکھتے ہیں وہی پہچان کر بتائیں گے کہ کون سے روایت اسرائیلیات میں سے ہے، عوام کے لیے روایات میں سے اسرائیلی روایات کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، اس لیے عوام کو اس بارے میں اس فن کے ماہر اہلِ علم سے ہی پوچھنا چاہیے، کیوں کہ بسا اوقات ایک ہی واقعہ کتبِ احادیث میں کسی صحابی سے بھی منقول ہوتاہے، لیکن وہ اسرائیلی روایت ہوتاہے، اور بعض مرتبہ کسی واقعے کا کوئی ایک جز یا کوئی حصہ اسرائیلی روایت ہوتاہے، جب کہ اسی واقعے کا کوئی ایک حصہ حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتاہے۔
حلیۃ الاولیاء میں ہے:
"حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الله بن خلة الصفار ثنا محمد بن يوسف الصوفي ثنا العباس بن إسماعيل الطامدي ثنا مكي بن إبراهيم بن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال: قرأت في التوراة - أو قال في صحف إبراهيم الخليل - فوجدت فيها: يقول الله يا ابن آدم ما أنصفتني خلقتك ولم تك شيئا وجعلتك بشرا سويا، خلقتك من سلالة من طين فجعلتك نطفة في قرار مكين، ثم خلقت النطفة علقة فخلقت العلقة مضغة فخلقت المضغة عظاما فكسوت العظام لحما ثم أنشأتك خلقا آخر. يا ابن آدم هل يقدر على ذلك غيري؟ ثم خففت ثقلك على أمك حتى لا تتبرم بك ولا تتأذى، ثم أو حيث إلى الأمعاء أن اتسعي، وإلى الجوارح أن تفرقي، فاتسعت الأمعاء من بعد ضيقها، وتفرقت الجوارح من بعد تشبكها. ثم أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمك فاستخلصك على ريشة من جناحه فاطلعت عليك فإذا أنت خلق ضعيف ليس لك سن يقطع ولا ضرس يطحن فاستخلصت لك في صدر أمك عرقا يدر لبنا باردا في الصيف حارا في الشتاء، واستخلصته لك من بين جلد ولحم ودم وعروق، ثم قذفت لك في قلب والدك الرحمة وفي قلب أمك التحنن، فهما يكدان عليك ويجهدان ويربيانك ويغذيانك، ولا ينامان حتى ينومانك. يا ابن آدم، أنا فعلت ذلك بك لا لشيء استأهلت به مني، ولا لحاجة استعنت بك على قضائها. يا ابن آدم، فلما قطع سنك وطحن ضرسك أطعمتك فاكهة الصيف في أوانها وفاكهة الشتاء في أوانها، فلما أن عرفت أني ربك عصيتني فادعني فإني قريب مجيب، واستغفرني فإني غفور رحيم."
(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، العباس بن إسماعيل، (10/ 399)، ط: مطبعة السعادة)
تفسیر ابن کثیر میں ہے :
"ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدتهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: {سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا} [الكهف: 22]، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: {قل ربي أعلم بعدتهم} فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس، ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: {فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا} أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب."
(تفسير ابن كثير، مقدمة المؤلف، 1/ 9، ط: دار طيبة، سعودية)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144603100097
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن