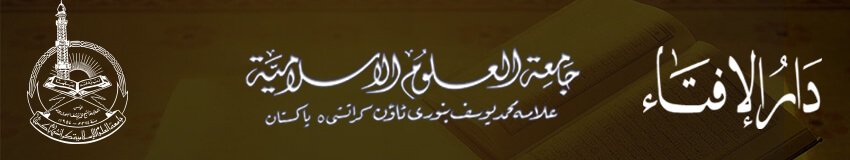
۱۔۲۔ کیا ہر حدیث کو عقل پر پیش کرنا ضروری ہے کہ اگر عقل کے موافق ہو تو اس کو ثابت سمجھا جائے ، اور اگر عقلِ سلیم کے خلاف ہو تو اس روایت کو موضوع مانا جائے؟ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث (صحیح بخاری، جلدِ اول، باب نمبر:۲۵۱) پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا عملی طریقہ کرکے سکھایا ،کیا یہ بات امہات المؤمنین کی شان کے مناسب ہے؟اگر چہ یہ پردے کے پیچھے ہی کیوں نہیں تھا ۔
اشکال کی وجہ یہ ہے کہ امہات المؤمنین کا معاملہ دیگر عورتوں جیسا نہیں :"يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاء"(الأحزاب:32)کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غسل کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ام المؤمنین سے پوچھنے کی ضرورت پڑی؟ان باتوں کی وجہ سے کچھ لوگ اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ہمیں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ حدیث بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن کچھ فاسد العقیدہ لوگ ہیں، اُن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، وہ اعتراضات کرتے ہیں ، حتی کہ میرے والد صاحب نے بھی ایک مجلس میں یہ اشکال کیا تھا، لہذا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ، دلائل کے ذریعے خوب واضح فرمائیں ۔
۳۔۴۔میرے والد صاحب نے کسی سے سنا تھا کہ سنت اور قرآن دونوں ہمارے پاس تواتر سے پہنچے ہیں، لیکن حدیث خبرِ واحد پر عمل کرنے سے پہلے اُسے قرآن ِ کریم پر پیش کرنا چاہیے، اگر قرآن ِ کریم کے موافق ہو تو اُسے قبول کیا جائے گا ورنہ نہیں،اسی طرح عقلِ سلیم پر بھی پیش کیا جائے گا، اگر عقلِ سلیم کے موافق ہو تو قبول کیا جائے گا ورنہ نہیں،کیا یہ درست ہے ؟نیز شریعت میں عقل کا کتنا اعتبار ہے؟
سوال میں جن امور کے متعلق دریافت کیا گیا ہے، ان تمام امور کا جواب حسبِ ترتیب درج ذیل ہے:
۱۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حضور کے غسل کے پانی کی مقدار اور طریقہ سکھانا، روایت کے مکمل الفاظ اور اُس کی تشریح :
سوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضور کے غسل کے پانی کی مقدار اور طریقہ سکھانے سے متعلق جو روایت ذکر کی گئی ہے، یہ روایت"صحيح البخاري"، "صحيح مسلم"، "مسند أحمد"ودیگر کتبِ احادیث میں مذکور ہے، کتبِ حدیث میں مذکورہ روایت کے مکمل الفاظ اور شارحین حدیث کی بیان کردہ تشریح کی روشنی میں اس روایت کی پوری حقیقت واضح ہوجا تی ہے۔ذیل میں مذکورہ روایت کے مکمل الفاظ اور شارحین ِ حدیث کی بیان کردہ تشریح ذکر کی جاتی ہے:
"صحيح البخاري"میں مذکورہ روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں:
"حدّثنا عبد الله بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنِيْ عبدُ الصّمد، قالَ: حدّثنِيْ شعبةُ، قالَ: حدّثنِيْ أبو بكر بنُ حفصٍ، قالَ: سمعتُ أبا سلمةَ، يقولُ: دخلتُ أنا وأخُو عائشةَ-رضي الله عنها- علَى عائشةَ-رضي الله عنها-، فَسألَها أخُوها عنْ غُسْلِ النّبِيِّ -صلّى الله عليه وسلّم-: فَدعتْ بِإِناءٍ نحواً مِنْ صاعٍ، فَاغتسلتْ، وأفاضتْ علَى رأسِها، وبينَنا وبينَها حجابٌ". قال أبو عبدِ اللهِ: قالَ يزيد بنُ هارون وبهزٌ والجُدِّيُّ عنْ شُعبةَ:"قدرِ صاعٍ".
(صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، 1/59، رقم:251، ط: دار طوق النجاة)
ترجمہ:
"(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی بھانجے حضرت ) ابو سلمہ (رحمہ اللہ ) کہتے ہیں: میں اور (حضرت) عائشہ رضی اللہ عنہا کے (رضاعی) بھائی (حضرت) عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے، آپ رضی اللہ عنہا کے (رضاعی) بھائی نے اُن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں دریافت کیا (کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل کیا کرتے تھے؟ اور تقریباً کتنی مقدار پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے؟) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاع جيسا (پانی کا) ایک برتن منگوایا، پھر اُس سے غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گویا غسل کی ابتداء سر پر پانی بہانے سے کی )اس حال میں کہ ہمارے اور اُن کے درمیان پردہ تھا‘‘۔
شارحین ِ حدیث کی بیان کردہ تفصیل سے قبل تمہیداً دو باتوں کا جاننا ضروری ہے:
۱۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں : میں نے حضرت عائشه رضي الله عنها سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا جو قرآنِ مجید ، میراث ، حلال وحرام ، شعر ، عرب کے واقعات اور انساب میں اُن سے ماہر ہو۔ حافظ ابنِ کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ صرف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ، بلکہ تمام عورتوں سے زیادہ علم رکھتی تھیں ، امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر تمام ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن اور تمام عورتوں کا علم ایک طرف ہو اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ہو تو وہ افضل (یعنی اُن سب سے بڑھ کر) ہے۔حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب کسی حدیث کے متعلق کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے پر اس کا حل ضرور نکل آتا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ایک صاع پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کو بعید سمجھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوکر اُس کے متعلق دریافت فرمایا، آپ رضی اللہ عنہا نے ایک صاع پانی منگوا کر پردے کی اوٹ میں اُس سے غسل فرمایا، جس سے اُن حضرات کا تعجب دور ہوگیا۔
۲۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آنے والے دونوں حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے محارم میں سے ہیں، اس لیے کہ حدیث کے راوی حضرت ابو سلمہ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی بھانجے ہیں ، کیوں کہ اًُنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی ہمشیرہ حضرت اُمِّ کلثوم بنتِ ابوبکر رضی اللہ عنہا کا دودوھا پیا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں دریافت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی ہیں ، اس لیے کہ "صحيح مسلم" کی روایت میں "أخوها من الرضاعة"(رضاعی بھائی )کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔
(صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، ... إلخ، 1/256، رقم:320، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت)
مذکورہ تمہید کے بعد شارحین ِ حدیث کی بیان کردہ تشریح ملاحظہ ہو:
۱۔قاضی عیاض اور علامه قرطبی رحمہما اللہ فرماتے ہیں: حدیث کے راوی حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ اور(حضور کے غسل کی مقدار اور طریقہ سے متعلق) سوال کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے محارم میں سے تھے، اُن کے لیے سر اور اور اوپر کے حصے (گردن اور کندھوں )کی طرف دیکھنا جائز تھا۔ حدیث کے ظاہر(سے) یہی (معلوم ہوتا)ہے کہ اُن دونوں حضرات نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غسل کے عمل کودیکھا ہے، یعنی صرف سر دھونے اور بدن کے اوپر کے حصے (گردن اور کندھوں) پر پانی بہانے کا مشاہدہ کیا ہے، کیوں کہ اگر وہ اس کا مشاہدہ نہ کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پانی طلب کرکے اُن کی موجودگی غسل کرنے کا کوئی مطلب نہ ہوتا، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکمل اوٹ میں یہ عمل کرتیں تو زبانی بتانے اور اس میں کوئی فرق نہ رہتا، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ عمل پردے کے اوٹ میں رہ کر کیا اس حال میں کیا ہے کہ جسم کا وہ حصہ (یعنی سر اور کندھوں کے علاوہ) جس کی طرف دیکھنا محرم کے لیے جائز نہیں ، وہ پوشیدہ تھا ۔ نیز علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "صحيح مسلم" کی اسی روایت میں راوی کا ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کے بالوں کی کیفیت کے بارے میں خبردینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بالوں کو دیکھا تھا ، اور محارم کے لیے اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ، تاہم حضرت ابن ِ عباس رضی اللہ عنہما سے کراہت کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے۔
۲۔علامہ کورانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک قاضی عیاض رحمہ اللہ کا جواب محلِ نظر ہے، اس لیے کہ محارم کے جسم کے اوپر کے حصہ کی طرف دیکھنا اگرچہ جائز ہے، لیکن اسے عام لوگ بھی پسند نہیں کرتے، چہ جائے کہ اس کی نسبت مجسمِ حیاء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف کی جائے، باقی رہی بات برتن(میں پانی طلب کرنے ) کی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس لیے طلب کیا تھا کہ اُن حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے پانی کی مقدار دکھائیں ، اُنہوں نے اسی کے لیے باقاعدہ غسل نہیں کیا تھا ، ہو سکتا ہے اُن کا پہلے سے غسل کا ارادہ ہو اور اتفاقاً یہ دونوں حضرات بھی آگئے ہوں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں پوچھا ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگرچہ پر دے کی اوٹ میں غسل فرمایا تھا، لیکن یہ زبانی تعلیم دینے سے زیادہ بلیغ تھا۔
۳۔حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ بحوالہ آثار الحدیث لکھتے ہیں:شراحِ حدیث کے مذکورہ جوابات سے ہٹ کر ایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ حدیث کے راوی نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ عرف اور محاورے کی بنیاد پر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غسل کا مشاہدہ کیا ہو، کیوں کہ عرف میں جب کسی سے اس طرح کا کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ کتنی مقدار پانی میں غسل کیا جاسکتا ہے ؟ یا فلاں کتنی مقدار پانی میں غسل کرتے تھے؟ تو اس کے جواب میں اگر وہ مخصوص برتن میں پانی سے عملاً غسل کرکے آ ئے اور بتائے کہ اتنی مقدار پانی سے غسل کیا تھا تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ پوچھنے والوں نے اُسے دیکھا ہو اور اسی طرح یہاں بھی ہوا ہو، مزیہ یہ کہ راوی کے الفاظ: " بينَنا وبينَها حجابٌ"(ہمارے اور اُن کے درمیان پردہ تھا) کے باوجود اعتراض کرنا اُن نفوسِ قدسیہ سے عداوت کے اظہار کے سوا اور کچھ نہیں ۔
(آثار الحدیث ، حدیث ِ غسل ام المؤمنین پر اعتراض ،ج:۲،ص:۵۱۹۔۵۲۰، ط: محمود پبلی کیشنز، اسلامک ٹرسٹ ، لاہور/ص: کشف الباری، کتاب الغسل، ص:۲۵۵، ط:مکتبہ فاروقیہ، شاہ فیصل کا لونی کراچی)
۴۔ حضرت شیخ الحدیث مولاناسلیم اللہ خان رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں:پھر یہ ضروری نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ غسل لباس کے بغیر کیا ہو، اس لیے کہ کسی ایک بھی صحیح روایت میں نہ تو اس کی صراحت موجود ہے ، اور نہ ہی کنایتاً اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اقرب یہ ہے کہ اُن کا یہ غسل لباس پہننے کی حالت میں تھا، لہذا ایک شرعی مسئلہ کی تعلیم کے لیے لباس پہننے ہوئے ہونے کے باوجود پردے کی اوٹ میں ہوجانا ، اُن پر اعتراض کی بجائے اُن کی حیاء اور احتیاط پر دلالت کرتا ہے۔
(کشف الباری، کتاب الغسل، ص:۲۵۷، ط:مکتبہ فاروقیہ ، شاہ فیصل کالونی کراچی)
۲۔حدیث کا عقلِ سلیم کے خلاف ہونا:
بلاشبه محدثین کرام رحمہم اللہ نے حدیث کے موضوع ہونے کے قرائن میں ایک قرینہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ روایت کردہ حدیث ،قرآنِ کریم ، یا خبرِ متواتر، یا اجماعِ قطعی ، یا عقلِ صریح کے اس طرح مخالف ہو کہ اس میں کوئی تاویل نہ ہو سکتی ہو۔ البتہ كسي حديث کے متعلق یہ طے کرنا کہ یہ حدیث قرآنِ کریم ، یا خبرِ متواتر، یا اجماع ِ قطعی ، یا عقلِ صریح کے اس طرح مخالف ہے کہ اس میں کوئی تاویل نہیں ہوسکتی ، اس لیے یہ حدیث موضوع(من گھڑت) ہے، یہ طے کرنا محدثینِ کرام وفقہاء عظام رحمہم اللہ کا منصب ہے،ہر کہ ومہ کو یہ اختیار نہیں۔ چنانچہ کتبِ موضوعات ومشتہرات میں اًُن حضرات نے اس نوع کی روایات کی چھان پھٹک کرکے اُن کی حیثیت واضح کردی ہے، تاہم ایک عامی کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے قصورِفہم کی بناپر کسی حدیث کو خلافِ عقل گردانے اور اُسے موضوع (من گھڑت) کہے، بلکہ ایک عامی کو اگر کسی حدیث کے متعلق ایسا خلجان ہو تو اُسے اپنی عقل وفہم کے استعمال کی بجائے اہلِ علم سے رجوع کرکے اپنی تسلی وتشفی کرنی چاہیے۔
۳۔ خبرِ واحد کو قرآنِ کریم پر پیش کرنا:
واضح رہے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ کی نصوص میں غور وفکر کرکے احادیث کے درمیان بظاہر تعارض کی صورت میں ترجیح وغیرہ مختلف اصول مرتب کیے ہیں، سوال میں جس صول :(’’ خبرِ واحد پر عمل کرنے سے پہلے اُسے قرآن ِ کریم پر پیش کرنا چاہیے ،اگر قرآن ِ کریم کے موافق ہو تو اُسے قبول کیا جائے گا ورنہ نہیں‘‘) کے متعلق دریافت کیا گیا ہے اُس کے متعلق ضروری تفصیل درج ذیل ہے:
جب دو حدیثوں میں بظاہر تعارض ہو اور اُن میں سے کسی ایک کے منسوخ کی صراحت موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں حنفیہ ترجیحی عمل اختیار کرتے ہیں اور اس ترجیحی عمل میں حنفیہ دیگر ادلہ شرعیہ سے موازنہ کرتے ہیں، اس موازنہ کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت خبرِ واحد کو قرآنِ کریم پر پیش کرنا ہے، یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ مبارکہ سے ہی ماخوذ ہے۔ حضرت امام ابویوسف رحمہ اللہ "كتاب الرد على سير الأوزاعي"میں لکھتے ہیں:"فَعليكَ مِنَ الحديثِ بِما تعرِفُه عامّةٌ، وإيّاكَ والشّاذَ مِنْهُ ... إلخ".( ایسی حدیث کو لازم پکڑو جس کو عام لوگ جانتے ہوں ، اور انوکھی حدیث سے گریز کرو)۔پھر امام ابویوسف رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا: "إنّ الحديثَ سيفشُوْ عنِّيْ، فَما أتاكُمْ عنِّيْ يُوافِقُ القرآنَ فَهُو عنِّيْ، ومَا أتاكُمْ عنِّيْ يُخالِفُ القرآنَ فَليسَ عنِّيْ".(یعنی لوگ میرے حوالے سے حدیث پھیلائیں گے، جس کو تم قرآن کے موافق پاؤ وہ میری حدیث ہے، اور جس کو تم قرآن کے مخالف پاؤ وہ میری حدیث نہیں)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی صحت معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کا قرآنِ کریم سے موازنہ کیا جائے ، اگر حدیث قرآنِ كريم کے مخالف ہو تو اُسے چھوڑ دیا جائے (یعنی اس پر عمل نہ کیا جائے‘‘۔
(كتاب الرد على سير الأوزاعي، ج:1، ص:24-25، ط: إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد- الهند/ اخبارِ آحاد اور اُن کی استدلالی حیثیت، ص:۱۳۱۔۱۳۲، ط: مکتبہ ابوبکر، بھروچ، گجرات ، الہند)
مذکورہ با لا سطور سے اصول :(’’ خبرِ واحد پر عمل کرنے سے پہلے اُسے قرآن ِ کریم پر پیش کرنا چاہیے ،اگر قرآن ِ کریم کے موافق ہو تو اُسے قبول کیا جائے گا ورنہ نہیں‘‘) کے متعلق ضروری تفصیل معلوم ہوگئی۔ تاہم یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ کسی حدیث کے متعلق یہ طے کرنا کہ یہ حدیث قرآنِ کریم کے مخالف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ حدیث قرآنِ کریم کے موافق ہے اس لیے اسے قبول کیا جائے گا، یہ حضرات فقہاء ومحدثین رحمہم اللہ کا منصب ہے، اور اُن حضرات نے کتبِ حدیث وفقہ وغیرہ کتب میں اسے بیان بھی کیا ہے، ایک عامی کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے قصورِفہم کی بناپر کسی حدیث کو قرآنِ کریم کے مخالف گردانے اور اسے متروک (یعنی ناقابلِ عمل) کہے، بلکہ ایک عامی کو اگر کسی حدیث کے متعلق ایسا خلجان ہو تو اُسے اپنی عقل وفہم کے استعمال کی بجائے اہلِ علم سے رجوع کرکے اپنی تسلی وتشفی کرنی چاہیے۔
۴۔خبرِ واحد کوعقلِ سلیم پر پیش کرنا:
انسانی عقل، فطرت، علم اور تجربے پر مبنی ہے، دین کی تفہیم میں اًُسے ایک معاون ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیوں کہ یہ دین کی سمجھ بوجھ ، احکام کو جانچنے اور اُن پر عمل کرنے میں معاون ہوتی ہے، تاہم یہ وحی کے برابر یا اُس پر غالب نہیں ، بلکہ وحی کے تابع ہے اور وحی اس سے برتر اور حاکم ہے۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:"وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا "(الاسراء:۸۵) ترجمہ: تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے) ،اس آیت ِ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی عقل محددود ہے اور ہربات کو فوراً سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:
"لَوْ كانَ الدينُ بِالرّأيِ لَكانَ أسفلُ الخُفِّ أولَى بِالمسحِ مِنْ أعلاهُ، وقَدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يمسحُ على ظاهرِ خُفَّيهِ".
(سنن أبي داود، رقم:162، ط: دار الرسالة العالمية)
(ترجمہ:اگر دین (کی بنیاد ) عقل پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا اوپر والے حصے کی بنسبت زیادہ مناسب ہوتا)، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل محدود ہے، اور شریعت کی بنیاد وحی پر ہے نہ کہ عقل ۔ اسی طرح شبِ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات آسمانوں اور اور اُن سے اوپر تک کی سیر کرنا بظاہر انسانی عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی تصدیق کی گئی ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ وحی کے مطابق اسے مانا جائے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، جنت، دوزخ اور فرشتوں کو بھی انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی ، لیکن قرآن وحدیث میں ان کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، اس لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔
مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شریعت میں عقل کی حیثیت دین کی تفہیم میں ایک معاو ن ذریعہ کی ہے، تاہم یہ قرآن وحدیث کے برابر یا اُس پرغالب نہیں، بلکہ اس کےتابع ہے، اس لیے عمومی طور پر یہ کہناکہ:( ’’خبرِ واحد کوعقلِ سلیم پر بھی پیش کیا جائے گا، اگر عقلِ سلیم کے موافق ہو تو قبول کیا جائے گا ورنہ نہیں‘‘) درست نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، جنت ، دوزخ وغیرہ امور سے متعلق اور ان کے علاوہ بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ عقلِ انسانی اُن کی سمجھ سے قاصر ہے، لیکن قرآن وحدیث میں اُنہیں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اُن کی تصدیق کرنا اور اُن پر ایمان لانا ضروری ہے۔
"حلية الأولياء"میں ہے:
"حدّثنا الحسنُ بنُ علّانَ الورّاقُ، ثنا جعفرُ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بنُ الحارثِ، ثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، ثنا هشامُ بنُ عروةَ عنْ أبيهِ، قالَ: مَا رأيتُ أحداً مِنَ النّاسِ أعلمَ بِالقرآنِ ولَا بِفريضةٍ ولَا بِحلالٍ ولَا بِحرامِ ولَا بِشعرٍ ولَا بِحديثٍ العربِ ولَا بِنسبٍ مِنْ عائشةَ -رضي الله تعالى عنها-".
(حلية الأولياء، النساء الصحابيات، ترجمة: عائشة زوج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، 2/49، ط: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر)
"البداية والنهاية"میں ہے:
"ومِنْ خصائِصِها أنّها أعلمُ نِساءِ النّبِيِّ -صلّى الله عليه وسلّم-، بَلْ هِي أعلمُ النِّساءِ علَى الإطلاقِ. قالَ الزّهرِيُّ: لَوْ جُمِعَ علمُ عائشةَ إلَى علمِ جميعِ أزواجِه، وعلمِ جميعِ النِّساءِ لَكانَ علمُ عائشةَ أفضلَ".
(البداية والنهاية، سنة ثمان وخمسين، وممن توفي فيها، 8/99، ط: دار إحياء التراث العربي )
"سنن الترمذي"میں ہے:
"حدّثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، قالَ: حدّثنا زياد بنُ الرّبيعِ، قالَ: حدّثنا خالد بنُ سلمة المخزوميُّ عنْ أبِيْ بُردةَ عنْ أبِيْ مُوْسَى، قالَ: مَا أشكلَ عَلَيْنَا أصحابَ رسولِ اللهِ -صلّى الله عليه وسلّم- حديثٌ قطُّ فسألَنا عائشةَ إلّا وجدنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْماً". هَذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ".
(سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب من فضل عائشة - رضي الله عنها-، 5/705، رقم:3883، ط: مصطفى البابي الحلبي -مصر)
"عمدة القاري"میں ہے:
"أبو سلمةَ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرّحمنِ بنِ عوفٍ ... وهُو ابنُ أختِ عائشةَ مِنَ الرّضاعةِ أرضعتْه أمُّ كلثومٍ بنتُ أبِيْ بكرٍ الصِّديقِ -رضي الله عنه-، فَعائشةُ خالتُه".
(عمدة القاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، 3/197، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت)
وفيه أيضاً:
"قولُه: (وأفاضتْ) أيْ: أسالتِ الماءَ علَى رأسِها، وهَذِه الجملةُ كَالتفسيرِ لِقولِه: (فَاغتسلتْ). قولُه: (وبينَنا وبينَها حجابٌ) جملةٌ وقعتْ حالاً".
(عمدة القاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، 3/198، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت)
"فتح الباري لابن حجر"میں ہے:
"قالَ القاضِيْ عياضٌ: ظاهرُه أنّهما رأيا عملَها في رأسِها وأعالِيْ جسدِها مِمّا يحلُّ نظرُه لِلمحرمِ، لِأنّها خالةُ أبِيْ سلمةَ مِنَ الرَّضاعِ أرضعتْه أختُها أمُّ كلثومٍ، وإنّما سترتْ أسافِلَ بدنِها مِمّا لَا يحلُّ لِلمحرمِ النظرُ إليهِ، قالَ: وإلّا لَمْ يكنْ لِاغتسالِها بِحضرتِهما معنًى، وفي فعلِ عائشةَ دلالةٌ علَى استحبابِ التعليمِ بِالفعلِ؛ لِأنّه أوقعُ في النّفسِ. ولمّا كان السّؤالُ محتملاً لِلكيفيّةِ والكميّةِ ثبتَ لَهُما مَا يدلُّ علَى الأمرينِ معاً أمّا الكيفيّةُ فَبِالاقتصارِ علَى إفاضةِ الماءِ وأمّا الكميّةُ فَبِالاكتفاءِ بِالصّاعِ".
(فتح الباري لابن حجر، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، 1/365، دار المعرفة - بيروت)
"فتح الباري لابن رجب"میں ہے:
"قالَ القرطبيُّ: ظاهرُ هَذا الحديثِ أنّهما - يعنِيْ: أبا سلمةَ وأخا عائشةَ - أدرَكا عملَها في رأسِها وأعلَى جسدِها مِمّا يحلُّ لِذِيْ المحرمِ أنْ يطّلِعَ عليهِ مِنْ ذواتِ محارمِه، وأبو سلمةَ ابنُ أخِيْها نسباً، والآخرُ أخُوها مِنَ الرّضاعةِ، وتحقّقا بِالسّماع كيفيةُ غسلِ مَا لَمْ يُشاهداهُ مِنْ سائرِ الجسدِ، ولَوْلَا ذلكَ لاكتفتْ بِتعليمِها بِالقولِ، ولَمْ تحتجَّ إلَى ذلكَ الفعلِ. قالَ: وإخبارُه عنْ كيفيّةِ شُعورِ أزواجِ النّبِيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- يدلُّ علَى رُؤْيتِه شعرَها، وهَذا لَمْ يختلفْ في جوازِه لِذِيْ المحرمِ، إلّا مَا يُحكى عنْ ابنِ عبّاسٍ مِنْ كراهةِ ذلكَ. انتَهى".
(فتح الباري لابن رجب، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، 1/249، ط: مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة)
"الكوثر الجاري إلى رياض البخاري"میں ہے:
"قال القاضي عياضٌ: ظاهرُ الحديثِ أنّهما رأيا أعالِيْ جسدِها مِمّا يحلُّ للمحارمِ النظرُ إليهِ؛ إذْ لَوْ لَمْ يكنْ كذلكَ رجعَ إلَى الوصفِ، فَلَا فائدةَ فِيْ إحضارِ الماءِ. وعِنْدِيْ فِيْ هَذا نظرٌ، لِأنّ النظرَ إلَى أعالِيْ الجسدِ وإنْ كانَ جائزاً إلّا أنّ أدانِي النّاسِ لَا ينظرونَ مِنْ أُمهاتِهم إلَى ذلكَ، فضلاً عنْ تلكَ الحضرةِ معدنُ الحياءِ. وأمّا طلبُ الإِناءِ لتُرِيَهم مقدارَ الماءِ، ورُبَّما كانتْ تُريدُ الغسلَ فاتّفقَ حضورُهما، ولَا شكّ أنّ غُسلَها وإنْ كانَ وراءَ الحجابِ، فَهُو أبلغُ مِنَ الوصفِ بِالقولَ".
(الكوثر الجاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، 1/409، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت)
"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"میں ہے:
"ومِنَ القرائنِ الّتي يُدرك بها الوضع ... ومنها: مَا يُؤخذُ مِنْ حالِ المرويِّ كأنْ يكونَ مُناقِضاً لنص القرآن أوِ السّنةِ المتواترةِ أوِ الإجماعِ القطعيِّ أوْ صريحِ العقلِ حيثُ لَا يقبلُ شيءٌ مِنْ ذلكَ التّأويلِ".
(نزهة النظر، كيف يعرف الوضع؟، ص:60، ط: مكتبة البشرى -كراتشي)
فقط والله أعلم
فتوی نمبر : 144511101382
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن