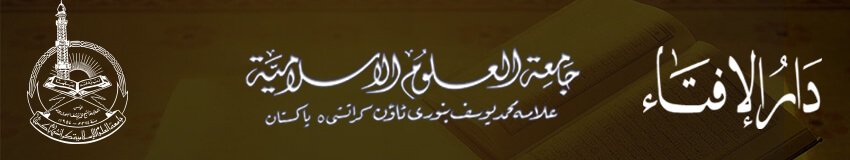
میں کرنسی کا کام کرتا ہوں۔میں دو طریقہ سے کام کرتا ہوں:
1) ٹریڈنگ یعنی میں لوگوں کو کرنسی فروخت کرتا ہوں۔ میرے پاس میرے بیرون ملک اکاؤنٹ میں رقم موجود ہوتی ہے اور جب کوئی ڈالر مانگنے آتا ہے تو میں اس کو ڈالر فروخت کرتا ہوں اور وہ جو مجھے اکاؤنٹ بتاتا ہے اس میں ٹرانسفر کردیتا ہوں اور وہ مجھے پاکستانی کرنسی ادا کردیتا ہے ۔ کیش کی صورت میں ڈالر نہیں دیتا۔ اور چونکہ یہ ڈالر کی خرید و فروخت بیرون ملک اکاؤنٹوں میں ہوتی ہے اور حوالہ کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ ڈالر کے انٹر بینک یا اوپن مارکٹ ریٹ پر نہی کرتے بلکہ حوالہ کا جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں مثلا ابھی ڈالر کا ریٹ ۲۷۹ چل رہا ہے تو ہم لوگوں سے معاملہ ۲۸۹ سے ۲۹۱ تک کرتے ہیں۔
میں جو ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں اس میں کچھ وقت لگتا ہے ۱۵ منٹ سے لیکر ایک گھنٹہ تک کا وقت لگ جاتا ہے یعنی جس مجلس میں سودا ہوتا ہے اسی مجلس میں ڈالر اس کے بتائے گئے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔اب میرا سوال یہ ہے کہ:
الف) میرا اس طرح ڈالر کی تجارت کرنا درست ہے یا نہیں؟
ب) اگر درست نہیں ہے تو پھر اس کا متبادل طریقہ کیا ہے؟ کیا قرض کا معاملہ کرنا درست ہوگا؟
ج) قرض کا معاملہ کرنے کی صورت میں اوپن مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت پر ڈالر فروخت کرنا درست ہوگا؟
د) قرض کا معاملہ کرنے کی صورت میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ سمجھانا کہ بیع کی جگہ قرض کا معاملہ کریں گے مشکل کام ہےتو کوئی ایسی تعبیر تجویز کردیجیے جس ے بیع ہو ہی نہ اور معاملہ خود ہی قرض کا بن جائے۔
۲) بعض مرتبہ میرے پاس ڈالر نہیں ہوتےاور جب کوئی ڈالر مانگنے آتا ہے تو میں کسی اور شخص (زید) سے ریٹ معلوم کرلیتا ہوں اور جو مانگنے آتا ہے اس کو اپنا نفع رکھ کر ریٹ بتا دیتا ہوں مثلا وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈالر ۲۸۷ کا ملے گا تو میں آگے ۲۸۹ یا ۲۹۰ یا ۲۹۱ کا ریٹ بتاتا ہوں (جتنے زیادہ میں خریدار مان جائے) اور جب وہ بات فائنل کرتا ہے تو میں اس سے وہ اکاؤنٹ نمبر معلوم کرتا ہوں جس اکاؤنٹ میں پیسے پہنچانے ہیں پھر وہ اکاؤنٹ نمبر زید کو بتاتا اور زید اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے۔ پھر جو پاکستانی کرنسی مجھے خریدار سے وصول ہوئی ہوتی ہے اس میں سے میں ۲۸۷ کے حساب سے زید کو ادائیگی کردیتا ہوں اور باقی جو ۲، ۳ یا ۴ روپے بچ جاتے ہیں وہ میرا نفع ہوجاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ:
الف) کیا یہ معاملہ درست ہے؟یعنی میرے حق میں یہ معاملہ بیع کے طور پر کرنا یا کمیشن کے طور پر کرنا جائز ہے یا نہیں؟
ب) کمیشن کے طور پر کرنے کی صورت میں کمیشن میرا متعین نہیں ہوتا بلکہ جتنے مہنگا میں بیچوں گا اتنا زیادہ میرا کمیشن ہوگا کیا یہ درست ہے؟
ج) اس معاملہ میں بھی زید جو متعلقہ اکاؤنٹ میں ڈالر ٹرانسفر کرتا ہے وہ معاملہ کی مجلس میں نہیں ہوتے بلکہ ۱۵ منٹ سے ۱یک گھنٹہ یا کچھ اس سے زیادہ وقت لگ جاتا ہےتو زید اور خریدار کے درمیان معاملہ درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میرا کمیشن لینا جائز ہوگا؟
د) اگر زید اور خریدار کے درمیان معاملہ درست نہیں ہے تو پھر کیا اس معاملہ کو قرض کے طور پر کرنا جائز ہوگا اور اگر قرض کے طور پر جائز ہوگا تو پھر کیا اس صورت میں میرےلیے کمیشن کے طور پر معاملہ کرنا جائز ہوگا؟ اگر میرے لیے قرض دلانے پر کمیشن لینا جائز نہیں ہے تو پھر متبادل کیا ہے؟
۱) الف) واضح رہے کہ کرنسی کی تجارت درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ معاملہ ہاتھ در ہاتھ کیا جائے یعنی جانبین کی طرف سے مطلوبہ کرنسی پر قبضہ ہوجائے مثلا زید بکر سے پاکستانی کرنسی کے بدلہ ڈالر خرید رہا ہے تو ضروری ہے کہ زید سودے کی مجلس میں ڈالر پر قبضہ کرلے اور بکر پاکستانی کرنسی پر قبضہ کرلے۔لہذا صورت مسئولہ میں سائل کا ڈالر کی خرید و فروخت کا معاملہ اس طرح کرنا کہ سودے کی مجلس میں جانبین کی طرف سے مطلوبہ کرنسی کا تبادلہ نہ ہو بلکہ ۱۵ منٹ سے ایک گھنٹہ کے بعد خریدار کے بتائے گئے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی جائے شرعا درست نہیں ہے۔
۱) ب،د) قرض کا معاملہ کرنا درست ہوجائے گا اور معاملہ یوں کرلیا جائے کہ سائل لوگوں سے کہہ دے کہ میں آپ کو فلاں جگہ یا فلاں اکاؤنٹ میں اتنی رقم پہنچا دوں گا اور اس کے بدلہ پاکستانی کرنسی وصول کرلوں گا۔پھر سائل مطلوبہ رقم مطلوبہ مقام یا اکاؤنٹ میں پہنچا دے اور اس کے پھر اس شخص سے پاکستانی کرنسی وصول کرلے۔
۱) ج)شق نمبر (ب،د) میں بتائے گئے طریقہ پر معاملہ کرنے کی صورت میں اوپن مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پر وصولی شرعا جائز نہیں ہوگی یعنی جس مقام پر پاکستانی کرنسی وصول کر رہا ہے وہاں ڈالر کے اوپن مارکیٹ یا انٹر بینک ریٹ کے مطابق پاکستانی کرنسی وصول کر لے۔اوپن مارکٹ سے زیادہ ریٹ پر وصول کرنا شرعا سود ہوگا۔
۲) الف،ج) مذکورہ معاملہ بیع کے طور پر کرنا سائل کے درست نہیں ہے بلکہ یہ بیع باطل ہے کیونکہ سائل جب سودا کرتا ہے اس وقت سائل کی ملکیت میں ڈالر موجود ہی نہیں ہوتے اور جو چیز ملکیت میں ہی نہ ہو اس کا بیچنا شرعا بیع باطل ہے۔
نیز کمیشن کے طور پر بھی اگر سائل معاملہ کرتا ہے یعنی زید اور خریدار کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ کروانے پر کمیشن وصول کرتا ہے تو پھر زید کے لیے یہ کمیشن جائز ہوگا بشرطیکہ زید اور خریدار کے درمیان کرنسی کی خرید و فروخت کا معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہو یعنی سودے کی مجلس میں ہی خریدار کو ڈالر مل جائیں اور زید کو پاکستانی کرنسی مل جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا بلکہ کرنسی کے تبادلہ میں کچھ وقت لگ جاتا ہے تو پھر سائل کے لیے کمیشن بھی حلال نہیں ہوگا کیونکہ یہ کمیشن ایک فاسد معاملہ کروانے کی اجرت بن جائےگا جو کہ شرعا حلال نہیں ہوگا۔
ب) شق نمبر الف کے مطابق جس صورت میں کمیشن لینا جائز ہے اس صورت میں کمیشن کا متعین کرنا ضروری ہے مثلا 100 ڈالر دلوانے پر ایک ڈالر کمیشن لوں گا یا ایک فیصد یا دو فیصد کمیشن لوں گا۔ سائل جس طرح کمیشن کا معاملہ کرتا ہے کتنا مہنگا بک جائے گا اتنا کمیشن ہوگا یہ درست نہیں ہے۔
د) اگر تبادلہ سودے کی مجلس میں نہیں ہوتا تو پھر زید اور خریدار کے درمیان ہونے والا معاملہ درست نہیں ہے لہذا پھر اس صورت میں بھی بیع کی جگہ قرض کا معاملہ کرنا ہوگا اور ڈالر کے بدلہ پاکستانی کرنسی کی وصولی اوپن مارکٹ ریٹ کے حساب سے ہی کرنی ہوگی جیسے کے سوال نمبر ایک کے جواب میں تفصیل گزر چکی ہے۔نیز زید اور خریدار کے درمیان قرض کا معاملہ ہونے کی صورت میں سائل کے لیے کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ کمیشن کا جواب خرید و فروخت کے معاملہ کے ساتھ مخصوص ہے، جب زید اور خریدار کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہورہا بلکہ قرض کا معاملہ ہورہا ہے تو پھر کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔
فتاوی شامی میں ہے:
"(ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء
(قوله: بالبراجم) جمع برجمة بالضم: وهي مفاصل الأصابع ح عن جامع اللغة. (قوله: لا بالتخلية) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية، واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم، حتى لو وضعه له في كفه أو في جيبه صار قابضا.
(قوله: قبل الافتراق) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهما، والتقييد بالعاقدين يعم المالكين والنائبين، وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم اعتبار المجلس، ومن ثم قالوا إنه لا يبطل بما يدل على الإعراض، ولو سارا فرسخا ولم يتفرقا، وقد اعتبروا المجلس في مسألة هي ما لو قال الأب اشهدوا أني اشتريت الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل كذا عن محمد؛ لأنه لا يمكن اعتبار التفرق بالأبدان نهر.
وفي البحر: لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم يجز؛ لأنهما مفترقان بأبدانهما."
(کتاب البیوع، باب الصرف، ج :۵، ص :۲۵۷، ایچ ایم سعید)
فتاوی شامی میں ہے:
"(باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز لما مر»
(قوله فإن نقد أحدهما جاز إلخ) نقل المسألة في البحر عن المحيط لكنه وقع فيه تحريف حيث قال: وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جاز وصوابه لم يجز كما عبر الشارح، ونبه عليه الرملي ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة في مسألة بيع فلس بفلسين بأعيانهما أن محمدا ذكرها في صرف الأصل، ولم يشترط التقابض، وذكر في الجامع الصغير ما يدل على أنه شرط فمنهم من لم يصحح الثاني، لأن التقابض مع التعيين شرط في الصرف، وليس به ومنهم من صححه، لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه، وحكم الثمن من وجه فجاز التفاضل للأول واشترط التقابض للثاني اهـ وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين فقوله: فإن نقد أحدهما جاز قول ثالث لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قولا آخر، لأن ما في الأصل لا يمكن حمله، على أنه لا يشترط التقابض، ولو من أحد الجانبين، لأنه يكون افتراقا عن دين بدين وهو غير صحيح. فيتعين حمله على أنه لا يشترط منهما جميعا بل من أحدهما فقط.
فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين، وما في الجامع اشتراطه منهما، ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القبض في المجلس فلو غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله لما مر فيه نظر.
[تنبيه] سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط قال: فلا يغتر بما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم لا يجوز إسلام موزون في موزون وإلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا اهـ.
قلت: والجواب حمل ما في فتاوى قارئ الهداية، على ما دل عليه كلام الجامع من اشتراط التقابض من الجانبين فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في الأصل، وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها شبه بالثمن، ولا يصح السلم في الأثمان ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفي بالقبض من أحد الجانبين تأمل."
(کتاب البیوع، باب الربا، ج :۵، ص :۱۷۹، ایچ ایم سعید)
فتاوی شامی میں ہے:
"وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع والثمن»
(قوله: وأما الفلوس الرائجة) يستفاد من البحر أنها قسم رابع حيث قال: وثمن بالاصطلاح، وهو سلعة في الأصل كالفلوس، فإن كانت رائجة فهي ثمن وإلا فسلعة اهـ ط."
(کتاب البیوع، باب الصرف، ج :۵، ص :۲۷۲، ایچ ایم سعید)
العقود الدریۃ فی تنقیح الحامدیۃمیں ہے:
"(سئل) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت زوج سوار ذهب معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ بالوكالة عن موكلته ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن المجلس من غير قبض وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور صرفا باطلا والإبراء غير جائز؟
(الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع المذكور صرفا باطلا؛ لأنه يشترط فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض؛ لأنه في معنى الفسخ فلا يصح الإبراء كما في البحر والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك من المعتبرات."
(کتاب البیوع، باب الصرف، ج نمبر ۱، ص نمبر ۲۸۲،دار المعرفۃ)
بدائع الصنائع میں ہے:
"(وأما) السلم في الفلوس عددا فجائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا يجوز بناء على أن الفلوس أثمان عنده فلا يجوز السلم فيها، كما لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وعندهما ثمنيتها ليست بلازمة بل تحتمل الزوال؛ لأنها ثبتت بالاصطلاح فتزول بالاصطلاح، وإقدام العاقدين على عقد السلم فيها مع علمهما أنه لا صحة للسلم في الأثمان اتفاق منهما على إخراجها عن صفة الثمنية فتبطل ثمنيتها في حق العاقدين سابقا على العقد وتصير سلعا عددية فيصح السلم فيها كما في سائر السلع العددية كالنصال ونحوها."
(کتاب البیوع، فصل فی الشرط الذی یرجع المسلم، ج نمبر ۵، ص نمبر ۲۰۸، دا ر الکتب العلمیۃ)
فتاوی شامی میں ہے:
"دفع دراهم إلى رجل وقال: أنفقها ففعل فهو قرض."
(کتاب الہبہ، ج نمبر ۵، ص نمبر ۷۰، ایچ ایم سعید)
فتاوی شامی میں ہے:
"وذكر القدوري في شرحه إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك البلد، فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه، وإن كان البلد لا ينفق فيها وجب القيمة اهـ.
وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة، فلذا أوجب القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمنية بالكساد، كما قدمناه وبهذا ظهر أنه لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كريال الفرنجي في زماننا فالواجب رد مثلها، وإن كانا في بلدة أخرى، لأن ثمنية الفضة لا تبطل بالكساد، ولا بالرخص أو الغلاء ويدل عليه ما قدمناه عن كافي الحاكم من أنه لا ينظر إلى غلاء الدراهم، ولا إلى رخصها هذا ما ظهر لي فتأمل وانظر ما كتبناه أول البيوع."
(کتاب البیوع، باب المرابحہ، فصل فی القرض، ج نمبر ۵،ص نمبر ۶۳، ایچ ایم سعید)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"المديون إذا قضى الدين أجود مما عليه لا يجبر رب الدين على القبول كما لو دفع إليه أنقص مما عليه، وإن قبل جاز كما لو أعطاه خلاف الجنس وهو الصحيح."
(کتاب البیوع،باب تاسع عشر، ج نمبر ۳ ، ص نمبر ۲۰۴، دار الفکر)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"ولو استقرض الفلوس أو العدالي فكسدت قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - عليه قيمتها يوم القبض وقال محمد - رحمه الله تعالى - عليه قيمتها في آخر يوم كانت رائحة وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقوله أقرب إلى الصواب في زماننا كذا في المحيط."
(کتاب البیوع،باب تاسع عشر، ج نمبر ۳ ، ص نمبر ۲۰۴، دار الفکر)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"رجل أقرض الدراهم البخارية ببخارى ثم لقي المستقرض في بلدة لا يقدر على تلك الدراهم قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأخذ قيمتها وقيل هذا إذا لقيه في بلد تنفق تلك الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا. وأما إذا كانت لا تنفق في هذه البلدة فإنه يغرم قيمتها كذا في فتاوى قاضي خان."
(کتاب البیوع،باب تاسع عشر، ج نمبر ۳ ، ص نمبر ۲۰۴، دار الفکر)
محیط برہانی میں ہے:
"وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذا أخذ المقرض المستقرض في بلدة أخرى، فإن شاء أخذه حتى يؤديه في الموضع الذي استقرضه، وإن شاء أخذه بقيمة ذلك الموضع ههنا، وإن أبى المستقرض أن يعطيه القيمة أجبر عليه. وروى إبراهيم عن محمد: رجل استقرض من آخر طعاماً بالعراق، فأخذه المقرض بمكة، قال أبو يوسف: عليه قيمته يوم أقرضه، وقال محمد: عليه قيمته بالعراق يوم اختصما، وليس عليه أن يرجع معه إلى العراق ويأخذ طعامه.
في «القدوري» : إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر على البخارية، فإن كان ينفق في ذلك البلد، فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهباً وجائياً ويستوثق منه، وإن كان في بلدة لا ينفق وجب القيمة."
(کتاب البیوع، فصل ثالث و عشرون، ج نمبر ۷، ص نمبر ۱۳۰، دار الکتب العلمیۃ)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"رجل أقرض رجلا ألف درهم وقبضها المستقرض ثم إن المقرض قال للمستقرض اصرف الدراهم التي لي عليك بالدنانير فإن عين له شخصا بأن قال له مع فلان ففعل جاز بالإجماع، وإن لم يعين شخصا ففعل قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يجوز على المقرض وقال يجوزفإن أراد الطالب أن يأخذ الدنانير من المستقرض ودفع إليه المستقرض باختياره جاز ذلك وهذا عندهم جميعا كذا في المحيط."
(کتاب البیوع،باب تاسع عشر، ج نمبر ۳ ، ص نمبر ۲۰۵، دار الفکر)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 144603100210
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن