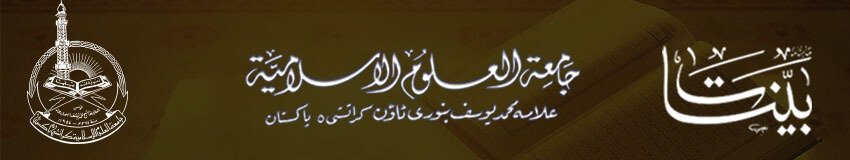
صوفیاء کا مشہور قول ہے کہ: ’’الطُّرُقُ اِلَی اللہِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ‘‘ یعنی حق تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس، لیکن ہر ایک کی تلاش کا منتہا اور طلب کی غایت ایک ایسا راستہ ہوتا ہے، جو’’اقرب‘‘ (Nearest) بھی ہو، ’’اسہل‘‘ (Easiest) بھی ہو اور ’’اسلم‘‘(Safest) بھی!
کیا کوئی ایسا راستہ واقعتاً موجود ہوسکتا بھی ہے یا نہیں؟ یا یہ محض ایک خیالِ خام و ناپختہ ہے یا ایک حسیں خواب ہے! کیا مجاہداتِ شاقّہ کے بغیر بھی کوئی آسان ترین طریق سے حق تعالیٰ کو پاسکتا ہے؟ کیا ایسا اس دور میں بھی ممکن ہے؟ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ایسا طریق یقیناً موجود ہے جو ’’ اقرب‘‘ بھی ہے، ’’اسہل‘‘ بھی اور ’’اسلم‘‘ بھی!
یہ تین ایسی خصوصیات (Qualifications) ہیں کہ ہر ایک طالبِ منزل جن چیزوں کا شعوری یا لاشعوری طور پر طالب ہوتا ہے، وہ یہی تین ہیں!
دنیوی قاعدے قوانین تو یہی ہیں کہ جو شے جتنی عظیم ہوگی، اس کے حصول میں اسی قدر دقتوں، تکلیفوں اور مشقتوں کا سامنا ہوگا، لیکن حق تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اپنے قرب ورضا و خوشنودی جیسے سب سے عظیم ترین مقصد کے حصول کے لیے ایسے آسان ترین راستوں کی جانب نسلِ انسانی کی راہنمائی فرماتے رہے اور فرماتے چلے جارہے ہیں کہ اقویاء بھی منزل یاب ہورہے ہیں اور ضعفاء بھی!
فخرالدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے اقرب و اسہل راستے کی خواہش و طلب کا اظہار فرمارہے ہیں کہ:
صنما! رہِ قلندر سَزد اَر بمَن نُمائی
کہ دَراز و دُور دِیدم رَہ و رسمِ پارسائی
اے شیخ! مجھے قلندری کا راستہ دکھائیے، کیونکہ یہ پارسائی کا راستہ دور بھی ہے اور طویل بھی۔‘‘
’’رہِ پارسائی‘‘ کو دراز پاکر اور دور دیکھ کر ’’پارسائی‘‘ کے اس طول و طویل راستے کے بجائے ’’قلندری‘‘ کے قصر و قصیر راستے کی طلب اور خواہش جیسے عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کس طالبِ مولیٰ کے سینے میں یہ ہُوک نہیں اُٹھتی؟! کس سالک کی یہ حسرت و تمنا نہیں ہے؟! ایسا ہی ایک قریب ترین اور آسان ترین راستہ موجود ہے جو ہر ایک رہروِ طریق کی رسائی میں بھی ہے اور اس پر چلنا ہمت و طاقت میں بھی!
ایک ایسا ہی اقرب و اسہل و اسلم طریق طریقِ اعترافِ ذنوب، اعترافِ خطا و قصور ہے۔ اس راہ سے بہتوں نے حق تعالیٰ کو پایا اور بہت سے اب بھی پارہے ہیں اور آج بھی بہتوں کو اس طریقہ سے یہ مقصد حاصل ہوسکتا ہے۔
’’ اقرب‘‘ اس لیے کہ ذنب تو انسان کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے کہ ہر وقت ہی ذنوب کا صدور ہو رہا ہے، خطائیں اور قصور ہورہے ہیں، ہوتے چلے جارہے ہیں، تو جیسے ہی خطا ہوئی اور حق تعالیٰ کے سامنے اعترافِ خطا اور توبہ ہوئی تو حق تعالیٰ کی عطا ہوئی، کرم ہوا، قربِ حق نصیب ہوا! کس قدر اقربیت ہے کہ یہاں ذنوب جدا نہیں ہورہے، معصیتیں الگ نہیں ہورہیں، اعتراف کرتے ہی توبہ کرتے ہی قرب الٰہی کا حصول ہورہا ہے، رضائے الٰہیہ حاصل ہورہی ہے اور قرب و رضا کے سوا منزل کیا ہے! اس سے زیادہ اقربیت منزل کی کیا ہوسکتی ہے کہ خطا و معصیت نے حق تعالیٰ سے جدا کیا، اعتراف و توبہ سے پھر واصل ہوگئے، اِدھر معصیت فراق کا باعث بنی، اُدھر اعتراف و توبہ وصال کا سبب !
’’اسہل‘‘ اس لیے کہ اس میں نہ کوئی لمبے چوڑے مجاہدے ہیں، نہ کوئی مراقبات و اَشغال میں سے گزارا جارہا ہے، صرف زبان سے بلکہ زبان سے بھی نہ کہے تو دل میں ہی اعتراف اور توبہ سے منزل یاب ہورہے ہیں۔
’’ اسلم‘‘اس لیے کہ اس راہ میں کوئی خطرات، کوئی گمراہیوں کا گزر نہیں ہے، جیسے اس راہ میں گوناگوں قسم کے خطرات سالکین کو پیش آتے ہیں اور نفس و شیطان کی فریب کاریوں اور دھوکہ دہیوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے اور کتنوں کیسوں کو قعرِ مَذَلّت اور قعرِ مُضِلّت میں گرایا جاتا ہے اور اب بھی گرایا جارہا ہے، اس کے برعکس رہروانِ طریقِ اعترافِ خطا و قصور والوں کو ان کی معصیتوں، ندامتوں اور شرمندگیوں کے بوجھ نے ہی ان کے دعووں کے پندار کی گردن توڑ رکھی ہے اور فنائیت نقدا نقد حاصل ہے۔ حضرتِ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نورانی حجابات، ظلمانی حجابات سے اشد ہیں۔ یہ ظلمانی حجابات تارِ عنکبوت ہیں، اعتراف و توبہ کی جنبش سے عنکبوتی حجاباتِ ظلمانیہ رفع ہوجاتے ہیں اور ’’وجہُ اللہ‘‘پیشِ نظر!
حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ:’’ ایک صوفی کو نور منکشف ہوا اور وہ اسے نورِ الٰہی سمجھ کر کئی برس تک اس کی عبادت میں مشغول رہا، جب بعد میں اس پر یہ کھلا کہ یہ تو اس کی اپنی روح کا نور تھا تو پھر توبہ و استغفار میں مشغول رہا!‘‘ اگرچہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا Litmus Test لکھا ہے، جس سے حق و باطل میں رحمانی و شیطانی خطرات میں امتیاز ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ ایسے کسی انکشاف کے بعد نفس کی حالت پر غور کرے کہ عجز و انکسار غالب آتا ہے یا عجب و پندار! ’’ناز‘‘ کی حالت ہوتی ہے یا ’’نیاز‘‘کی! اگر ’’نیازمندی‘‘ کی حالت پیدا ہو تو ٹھیک، وگرنہ اُسے دھوکہ خیال کرے، لیکن اس امتیازِ انکسار و پندار میں بھی اگر دھوکہ کھا گیا تو پھر!
بیسویں صدی میں حق تعالیٰ نے برصغیر کو ایک ایسی ہستی سے نوازا جس کی نگاہِ دُور بیں و باریک بیں نے وہ کچھ دیکھا جو بہت کم کی نظر میں آیا اور صرف خود ہی نہیں دیکھا، بلکہ اصلاحِ نفس و قلب کے اصولوں کی صورت، شکل میں ایسے دُور بینی و باریک بینی شیشے عنایت فرمائے جن کو لگا لگا کر کم بیں بھی اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں جسے وہ مجددالملت و الدین جس کی نگاہ ’’یَنْظُرُ بِنُوْرِ اللہِ‘‘ کی حقیقت و عظمت پائے ہوئے تھی، اپنی نگاہِ روشن سے بے غبار دیکھ رہا تھا، ان کی اس بات پر سر دھنیے فرمایا کہ:
’’اگرچہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حق و باطل میں امتیاز کا ایک طریق لکھا ہے، لیکن تمہیں اس میں بھی دھوکہ دیا جاسکتا ہے، اس لیے تم بس ’’لَا‘‘ ہی پھیرنا، نفی ہی کرتے جانا، کسی بھی ایسی شے میں مشغول نہ ہونا!‘‘
اس بات کی قدر دانی وہی کرسکتا ہے جو اس راہ کے خوب رُو اور دلکُشا و رعنا دھوکوں سے واقف ہے کہ کس قدر بھیس بدل بدل کر شیطانی نفسانی دھوکوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے! أعاذنا اللہ تعالٰی۔
یعنی جو اَنوار کے دھوکے میں ڈال سکتا ہے تو کیا عجز و انکسار کے دھوکے میں نہیں ڈال سکتا!
اس بات سے یہ ثابت ہوگیا کہ اس راستے میں خطرات ہیں اور جس راستے کو یہاں بیان کیا جارہا ہے وہ ان خطرات سے خالی ہے، کیونکہ اس راہ میں شکستگی ہی شکستگی ہے، جو مشکل ہی کسی دھوکہ کو راہ پانے دیتی ہے۔
شیخ زکریا بن محمد الانصاریؒ ’’الفتوحات الإلٰہیۃ‘‘ میں رقم طراز ہیں کہ ’’قربِ الٰہی کے طریقے اگرچہ بہت سے ہیں، لیکن ہم انہیں تین انواع میں تقسیم کرسکتے ہیں:
’’پہلا طریقہ: اربابِ معاملات کا ہے، جس میں کثرتِ صوم و صلوٰۃ اور تلاوتِ قرآن وغیرہ ظاہری اعمال کی کثرت ہے اور یہ لوگ ’’اخیار‘‘کہلاتے ہیں۔
دوسرا طریقہ: اربابِ مجاہدات کا ہے، ان کے ہاں اخلاق کی تحسین، نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ اور جن امور کا باطن کی درستی و تعمیر سے تعلق ہو، ان کے لیے کوشش کرنا ہے اور یہ حضرات ’’ابرار‘‘ کہلاتے ہیں۔
تیسرا طریقہ: طریق السائرین إلی اللہ (یعنی اللہ کی طرف ہمیشہ سیر و سلوک میں مشغول رہنے والوں کا ہے) اور یہ لوگ اہلِ محبت میں سے ہیں اور ’’شطار‘‘ کہلاتے ہیں۔ یہ طریقہ دس اصولوں پر منحصر ہے، ان دس اصولوں میں سے پہلا اصول توبہ یعنی ندامت ہے۔
اس کی تکمیل (نفسانیت کو) جڑ سے اُکھاڑ دینے پر ہوتی ہے۔ ‘‘
ہمارا مقصود تیسرے طریقہ کے اس پہلے اصول کے متعلق ہے جو توبہ یعنی ندامت ہے۔ اس طریقِ اعترافِ قصور میں بھی نفسانیت کی جڑ کٹ جاتی ہے، اگر اُمُّ الرَّذائل کبر ہے تو اُمُّ الفضائل عجز و انکسارِ صادق ہے۔
انسان ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی اور اس خاکی پتلے میں ’’وَ نَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ‘‘سے حیات پھونکی۔ اُسے ’’علمِ اسماء کلہا‘‘ سے مزیّن کرکے ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور ملائکہ سے علمِ اسماء کے متعلق استفسار کیا، جواب سے عاجز ملائکہ، ’’لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا‘‘ کہہ کے عدمِ علم کے معترف ہوئے تو آدم علیہ السلام نے بتایا جو انہیں ’’الْعَلِیْم‘‘ نے سکھایا تھا۔ ملائکہ کو سجدہ ریزی کا حکم صادر ہوا، سب سجدہ ریز ہوئے إلا إبلیس۔ خلافتِ ارضی کے لیے چُنیدہ آدم( علیہ السلام ) سے خطائے اجتہادی ہوئی اور جنت سے خروج ہوا۔
حکمِ’’ہبط‘‘ آدم کو بھی ملا اور ابلیس کو بھی، لیکن آدم علیہ السلام کو ملا ’’خلیفۃ اللہ في الأرض‘‘ اور ’’کَرَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ‘‘ جیسی عظمتوں کے ساتھ اور ابلیس کو ملا ’’لَعْنَتِيْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ‘‘ اور ’’اِنَّکَ رَجِیْمٌ‘‘ کی ذلتوں کے ساتھ، یعنی آدم علیہ السلام اُترے ’’خلافتِ ارضی‘‘ اور ’’کرّمِیّت‘‘ کے ساتھ اور ابلیس اُترا ’’لعنتِ ابدی‘‘ اور ’’رجیمیّت‘‘ کے ساتھ۔
ایک خطا آدم علیہ السلام کی اور ایک خطا ابلیس کی اور صدورِ نفسِ خطا میں دونوں ظاہراً مشترک، ناں کہ حقیقتاً، لیکن ایک کو اجتبائیت اور کرّمیّت سے نوازا گیا اور ایک کو ’’لَعْنَتِيْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ‘‘ کا مژدہ سنایا گیا۔ اُس کا سبب سوائے اس کے کیا تھا کہ ’’آدم‘‘کا ’’آدمی طرزِ عمل‘‘ تھا، یعنی اعترافِ قصور، جس کا اظہار کیا ’’رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا‘‘کہہ کر اور ’’ابلیس‘‘ کا’’ابلیسی طرزِ عمل‘‘ تھا جس کا اظہار کیا ’’اَنَا خَیْرٌ مِّنْہُ‘‘ کہہ کر۔ ایک تو عدمِ اعترافِ قصور اور اس پر مستزاد یہ کہ ’’اَبٰی وَاسْتَکْبَرَ‘‘ کے بعد مصداق بنا ’’ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا‘‘ کا۔ ایک راہِ محبوبیتِ الٰہیہ ہے اور ایک راہِ مغضوبیتِ الٰہیہ۔ خطائے آدم پر تو انسان کی نگاہ جاتی ہے، لیکن اُس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، جہاں حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ: ’’عَصٰی اٰدَمُ رَبَّہٗ فَغَوٰی‘‘، اس سے اگلی آیت میں یہ بھی تو فرمایا ہے کہ: ’’ثُمَّ اجْتَبٰہُ رَبُّہٗ فَتَابَ عَلَیْہِ وَھَدٰی‘‘
دیکھیے! حق تعالیٰ معصیتِ آدم کے بعد اجتبائیتِ آدم کا ذکر فرمارہے ہیں اور فسقِ ابلیس کے بعد رجیمیّتِ ابلیس کا ذکر فرمارہے ہیں۔ ’’عَصٰی‘‘ اور ’’غَوٰی‘‘ تو بنی آدم کے خمیر میں ہے، لیکن اجتبائیت کی راہ ’’عَصٰی‘‘ اور’’غَوٰی‘‘ کو کچلنے سے نہیں، بلکہ ’’رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا‘‘ کے اعتراف سے کھلتی ہے اور رجیمیّت کی راہ ’’اَنَا خَیْرٌ مِّنْہُ‘‘ اور ’’اَبٰی وَاسْتَکْبَرَ‘‘ سے ہموار ہوتی ہے۔
اگرچہ خطاً تو دونوں مشترک ہیں تو کون سی ایسی بات ہے جس کی بدولت دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ بات ہی اصلِ بندگی ہے، وہی کیمیا ہے قلوب کی، وہی نسخۂ جراحتِ دل ہے۔ وہ’’کیمیا ‘‘ وہ’’نسخہ‘‘ ہے: اعترافِ قصور، اعترافِ ذنوب، اعترافِ نقص، اعترافِ تقصیر اور اعترافِ خطا کا۔
دیکھیے! حق تعالیٰ نے فرعون کے لیے ’’اِنَّہٗ طَغٰی‘‘ فرمایا اور آدم علیہ السلام کے لیے ’’فَغَوٰی‘‘ وہاں ’’فَغَوٰی‘‘ کے بعد ’’اجتبائیت‘‘ ہے، لیکن اُس کے بیچ اعترافِ قصور و ذنوب بھی ہے جو سبب ہے اجتبائیت کا اور فرعون کے معاملہ میں ’’طَغٰی‘‘ ہی ’’طَغٰی‘‘ ہے، بیچ میں کہیں اعترافِ قصور و ذنوب نام کو بھی نہیں ہے، اسی لیے ’’اجتبائیّت‘‘ کی جگہ ’’غرقیّت ‘‘ہے۔
جہاں تک معصیت کا تعلق ہے تو ذوقِ معصیت تو انسان کے خمیر میں ہے جس کا اظہار ’’کُلُّھُمْ خَطَّاؤوْنَ‘‘ کہہ کر کردیا گیا تو مسئلہ بنی آدم ’’خطا ‘‘ نہیں، ’’قصور‘‘نہیں، بلکہ عدمِ اعترافِ خطا و قصور ہے۔ خطائیں تو ہم سے ہوتی ہی رہیں گی تو اعترافِ خطا و قصور کرکے ہم کیوں ناں حق تعالیٰ کے ہاں اجتبائیت اور محبوبیت کا درجہ پالیں۔ آج بھی حق تعالیٰ وہی کے وہی ہیں، وہ بدلے نہیں ہیں، ’’لَنْ تَجِدَ لِسُنَّۃِ اللہِ تَبْدِیْلًا‘‘ کا وعدۂ الٰہی ہے، جس کا تخلُّف محال ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا، لیکن اُن کا عناد و تمرُّد بڑھتا ہی رہا تو بددعا کی اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو تمام بستی والوں نے دل سے توبہ کی اور بت توڑ ڈالے اور حضرت یونس ( علیہ السلام ) کو ڈھونڈا، لیکن نہ ملے۔
حضرت تھانوی ؒ نے فرمایا کہ:
’’پس چونکہ اس فرار کو انہوں نے اجتہادِ جائز سمجھا، اس لیے انتظار نص اور وحی کا نہ کیا، لیکن چونکہ امیدِ وحی کا انتظار انبیاء کے لیے مناسب ہے، اس ترکِ مناسب پر اُن کو یہ ابتلا پیش آیا، راہ میں ان کو کوئی دریا ملا، اور وہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلتے چلتے رک گئی، یونس ( علیہ السلام ) سمجھ گئے کہ میرا یہ فرارِ بلااذن ناپسند ہوا، اس کی وجہ سے کشتی رکی، کشتی والوں سے فرمایا کہ: مجھ کو دریا میں ڈال دو، وہ راضی نہ ہوئے، غرض قرعہ پر اتفاق ہوا، تب بھی ان ہی کا نام نکلا، آخر اُن کو دریا میں ڈال دیا اور خدا کے حکم سے ان کو ایک مچھلی نگل گئی۔ ‘‘
اس واقعہ میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ جب کشتی رکی تو نبیِ وقت ہو کر بھی یہ احساس بیدار ہوا کہ یہ قوم کو چھوڑ کر آنا درست نہیں تھا، یہ میری خطا کی وجہ سے کشتی رک رہی ہے اور قرعہ ڈال کر بھی جب آپ ہی کا نام نکلا تو دریا میں ڈال دیے گئے۔ ہم معصیتوں میں گھر کر ہمہ وقت معصیت کوشیوں کے باوجود خود کو کبھی قصوروار خیال نہ کریں اور وہ معصوم عن الخطا ہوکر بھی ایک ایسی بات جو مناسب نہ تھی، اسے اپنی خطا صرف سمجھا ہی نہیں، بلکہ اس کا اعتراف بھی کیا:
’’فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ‘‘
حضرت یونس علیہ السلام زبانِ حال سے جس مفہوم کو ادا کررہے تھے، حق تعالیٰ نے زبانِ قال سے وہ الفاظ کہلوادیے۔ سبحان اللہ! کیا پیغمبرانہ شانِ عبدیت ہے!بندہ ہونے کا مطلب، بندگی کا مفہوم، بندہ پن کسے کہتے ہیں، کیسے طرز و اندازِ یونس علیہ السلام سے مبرہن و روشن ہے!انبیاء کاملین کے ساتھ اگر ایسے معاملات نہ ہوتے تو ہم ناقصین کو مفہومِ بندگی کیا سمجھ آتا! غیر سلیم قلوب کے لیے ایسے واقعات کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے اور قلبِ سلیم والوں کو انہی واقعات سے کیسی لذّت، کیسا کیف و سرور، کیسا نشاط ہوتا ہے!کتنے کیسے عقدے وا ہوتے اور کیسے کتنے راز بے نقاب ہوتے ہیں! شعور و احساسِ خطا بھی پورا ہے اور اعترافِ خطا بھی ! اکثر اوقات ہمیں بھی احساسِ خطا ہوجاتا ہے، لیکن ایک ایسا نفسانی مانع آڑے آجاتا ہے کہ ’’احساس‘‘ سے ’’اعتراف‘‘ تک کا سفر طے نہیں ہوپاتا!
زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا، لیکن اس بچ جانے پر بھی اپنے نفس کی نزاہت و عصمت ثابت کرنے کے بجائے ’’وَمَآ اُبَرّیُٔ نَفْسِیْ‘‘سے اپنے نفس کی براءت سے براءت کا اعلان کررہے ہیں : ’’اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَۃٌ بِالسُّوْءِ‘‘ سے نفس کی حقیقت سمجھا رہے ہیں اور ’’اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ‘‘ سے بچنے کی علت ظاہر فرمارہے ہیں۔
معصومین عن الخطا والوں کا اگر یہ معاملہ رہا تو کون، کیسا، کہاں رہا جو زبانِ حال سے یا زبانِ قال سے ’’اَنَا اُبَرِّئُ نَفْسِیْ‘‘ کا دعویٰ کرے!
حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مظہرِ اتم و مظہرِ کامل، بشری انسانی قالب میں کمالاتِ انسانی کی وہ بلند ترین چوٹی کہ جس سے زیادہ انسانی عظمت و بلندی کا سوال ہی نہیں، جس ہستی کا مقامِ عالی یہ کہ ’’وَمَا یَفْعَلُ عَنِ الْہَوٰی‘‘ تو درکنار ’’وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْہَوٰی‘‘ کی سند پائے ہوئے ہیں، لیکن اسے یہ رنج و غم مستقل رہتا ہے کہ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور غم بھی اس قدر کہ اس غم کا ایک ذرہ اگر ہمارے قلوب پر پڑ جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوجائیں، اس غم کی ایک چھینٹ پڑ جائے تو قلوب جل کر راکھ ہوجائیں!
حق تعالیٰ نے اپنے محبوب عبدِ کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و اطمینان کے لیے یہ آیتِ مبارکہ اُتاری: ’’لِيَـغْفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَاَخَّرَ‘‘
اس آیت میں لفظِ ’’ذنب‘‘ اپنے اندر کس قدر معنویت سموئے لپیٹے ہوئے ہے!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جن پر ’’ذَنْب‘‘ کا اطلاق بھی نہیں ہوتا، کمالِ معرفتِ خداوندی اور کمالِ بندگی، کمالِ عشقی سے انہیں بھی ’’ذَنْب‘‘ ہی خیال فرمارہے ہیں اور حق تعالیٰ کا کیسا تعلقِ خاطر ہے کہ فرمایا: (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ جس کو ’’ذَنْب‘‘ خیال فرمارہے ہیں) ان سب اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کردیا!
فرض نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد اللہ اکبر، استغفراللہ، استغفراللہ، استغفراللہ فرمانے میں کیا اس بات کا اظہار نہیں کہ اے اللہ! آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی بہت ہی زیادہ ہے اور ہم سے حقِ بندگی ادا نہ ہوا، اس پر معافیوں کے طلب گار ہیں!سبحان اللہ! ہر ہر قول، ہر ہر فعل سے عبدیتِ کاملہ مترشح ہورہی ہے!
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تائیداتِ الٰہیہ اور صحبتِ نبوی کی برکت سے ایک خاص رنگ چڑھا ہوا تھا، ان تائیداتِ الٰہیہ و صحبتِ نبویہ کے باوصف جس رنگِ محمدی کے Shade کو اُن کی ذات و حیات میں جھلکتا ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا اور جنہوں نے خود کو قصد و اردہ سے اندھا بنا لیا تھا یا ان کی یرقان زدگی نے انہیں وہ رنگ دکھایا بھی تو کسی اور رنگ میں، وہ رنگ وہ لون تھا ’’رنگِ عبدیت‘‘، ’’رنگِ اعترافِ قصور‘‘ جو سراجاً منیرا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہر صحابیؓ/ صحابیہؓ کی شخصیتوں کے شیشوں میں سے جھلکا جو اپنی اصل میں ’’واحد‘‘ اور ہر ایک کے شخصی Mould شاکلہ کی وجہ سے ’’کثیر‘‘ ہوگیا، نورِ واحد مختلف رنگ کے شیشوں میں سے منعکس ہو کر ’’کثیر‘‘ شکلوں میں ظاہر ہوا، اس رنگِ اعترافِ قصور کے اظہار کے لیے صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں:
مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عُقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس میں ایک نصیحت یہ بھی موجود ہے: ’’وَابْکِ عَلٰی خَطِیْئَتِکَ‘‘ اپنی خطا پر روؤ، آنسو بہاؤ۔ یہاں رونے اور آنسو بہانے سے مراد ندامت و شرمندگی ہے اپنی خطاؤں معصیتوں پر!
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو مختلف مواقع پر مختلف پیرائے میں نصیحتیں وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں بے شمار اسرار و رموز ہیں، بہرکیف! یہاں اس کا موقع نہیں ہے، عُقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کی گئی نصائح میں یہ جو ایک نصیحت ’’وَابْکِ عَلٰی خَطِیْئَتِکَ‘‘ ہے، یہی میرا موضوع ہے کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ ایک طریق ایک شاہراہ ’’وَابکِ عَلٰی خَطِیْئَتِکَ‘‘ سے بھی کھلتی ہے اور بہتوں کے لیے یہ راہ اسی طرح کھلتی رہی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اور اس کے گھر نے اس کو سموئے رکھا اور وہ اپنی خطاؤں (و گناہوں) پر رویا (یعنی شرمندہ ہوا): ’’وَبَکٰی عَلٰی خَطِیْئَتِہٖ‘‘
مسند احمد ہی کی ایک اور حدیث میں ایک صحابی حضرت عمروبن العاص رضی اللہ عنہ کے وصال کا جو واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمروبن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دیکھا کہ والد پر ایک شدید گھبراہٹ طاری ہے: جَزَعًا شَدِیْداً، بیٹے نے دریافت کیا کہ: مَا ھٰذَالْجَزَعُ؟یہ گھبراہٹ اور پریشانی کیسی؟ آپ کو تو یہ مقام و مرتبہ حاصل رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے قریب بٹھاتے اور مختلف علاقوں میں عامل بنا کر بھیجا کرتے تھے۔
عمروبن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: ’’اَيْ بُنَیَّ! قَدْ کَانَ ذٰلِکَ‘‘ بیٹے! یہ سب کچھ ہوتا رہا، اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ آپ کامیرے ساتھ یہ تعلق مجھ سے محبت کی وجہ سے تھا یا میری تالیفِ قلبی کے لیے تھا: ’’اِنِّیْ وَاللہِ مَا اَدْرِیْ اَحُبّاً ذٰلِکَ کَانَ اَمْ تَاَلُّفاً یَتَاَلَّفُنِيْ۔‘‘
حدیث کے آخر میں یہ فرمایا کہ : ’’اللَّھُمَّ اَمَرْتَنَا فَتَرَکْنَا‘‘ یااللہ! تو نے ہمیں حکم دیے، ہم نے ان کی پرواہ نہ کی اور ’’نَھَیْتَنَا فَرَکِبْنَا‘‘ تو نے ہمیں بہت سے کاموں سے روکا، مگر ہم ان کا ارتکاب کرتے رہے، ’’ لَا یَسَعُنَا اِلَّا مَغْفِرَتُکَ‘‘ ہم تو تیری مغفرت ہی کے اُمیدوار اور طلب گار ہیں۔ یہی کہتے ہوئے اور اسی حالت میں وہ انتقال کرگئے۔
امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیرِ کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر تھے کہ اچانک حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: ’’یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ھٰذَا اَبُوْذَرٍّ قَدْ اَقْبَلَ‘‘ یہ جو آرہے ہیں ابوذر غفاریؓ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اَوَ تَعْرِفُوْنَہٗ؟‘‘ کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ تو آسمانی مخلوق ہیں، مدینہ کے لوگوں کو آپ کیسے جان گئے؟ ابوذر غفاریؓ کو آپ نے کیسے پہچان لیا؟ عرض کیا: ’’ھُوَ اَشْھَرُ عِنْدَنَا مِنْہُ عِنْدَکُمْ‘‘ مدینہ میں ان کی جتنی شہرت ہے، اس سے زیادہ یہ آسمان میں ہم فرشتوں کے درمیان مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’بِمَا ذَا نَالَ ھٰذِہِ الْفَضِیْلَۃَ؟‘‘ یہ فضیلت ان کو کیسے ملی؟ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ: ان کو یہ فضیلت دو اعمال سے ملی ہے، ایک تو یہ ’’لِصِغَرِہٖ فِيْ نَفْسِہٖ‘‘ یہ دل میں اپنے کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ دوسرا عمل ان کا یہ ہے : ’’وَکَثْرَۃِ قِرَاءَتِہٖ قُلْ ھُوَاللہُ اَحَدٌ‘‘ کہ یہ ’’قُلْ ھُوَاللہُ اَحَدٌ‘‘(سورۂ اخلاص) کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ (التفسیرالکبیر للرازي، منقول از علاجِ کبر لمولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ )
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ بارش کی دعا کروانے حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: اس بستی میں جو بارش نہیں ہورہی، وہ میری ہی بداعمالیوں کی وجہ سے نہیں ہورہی، اگر میں بستی سے نکل جاؤں گا تو بارش ہوجائے گی اور وہ بزرگ بستی سے باہر نکلے اور بارش شروع ہوگئی۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے، کسی نے اعلان کیا کہ اس مسجد میں جو سب سے زیادہ نالائق، بدترین، گناہ گار اور برا انسان ہو، وہ جلدی سے مسجد سے باہر آجائے۔ اس مسجد میں جتنے نمازی تھے، ان میں جو سب سے بڑے بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہ باہر آکر کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں میں ہی بدترین مسلمان ہوں۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حافظ جی مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور جب کبھی بچوں کو مار پیٹ کرلیتے تو فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی خواہ ہوجاتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یہ حافظ جی ہمیں دے دیجیے، ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، وہاں یہ پڑھائیں تو حضرت نے فرمایا: ایک ہی تو مسلمان ہے میرے پاس، وہ بھی تمہیں دے دوں!
ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ: میں اپنی معصیتوں کا اثر اپنی بیوی، غلام اور گھوڑے کے اخلاق میں محسوس کرتا ہوں۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ایک بزرگ جب ٹرین میں سوار ہوتے تھے تو حق تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ: میری بداعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ٹرین حادثہ کا شکار نہ ہوجائے۔
سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے ہیں اور رفاعیہ سلسلہ حضرت ؒ سے ہی منسوب ہے۔ حضرت ؒ نے صوفیاء کے جس گروہ کو سب پر ترجیح دی ہے، وہ ذلت و انکسار والوں کا گروہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے نزدیک ’’اسہل‘‘و ’’اقرب‘‘ و ’’اسلم‘‘ ہونے کی تینوں خصوصیات (Qualifications) کا حامل ہے!
حضرت ؒ نے اپنی کتاب ’’البنیان المشید‘‘ (مترجم مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ) میں فرمایا کہ:
’’ اے بزرگو! (صوفیاء کی) جماعتیں آج کل مختلف پارٹیاں بن گئی ہیں (کوئی اپنے کو صاحبِ حالات کہتی ہے، کوئی صاحبِ مقامات بتلاتی ہے، کوئی وحدۃالوجود کا دم بھرتی ہے، کوئی فناء و بقا وغیرہ کا) مگر یہ ناچیز احمد (رفاعی ؒ) تو ذلت و انکسار والوں اور مسکنت اور بے قراری والوں کے ساتھ رہے گا، (مجھے) اس کے سوا کچھ پسند نہیں۔
ھنیئاً لأرباب النعیم نعیمھم
و للعاشق المسکین مایتجرعٗ
’’دولت والوں کو ان کی دولت مبارک ہو اور عاشقِ مسکین کو ذلت و مسکنت کے تلخ گھونٹ مبارک ہوں۔‘‘
اس راہِ اعترافِ خطا و قصور پر چلنے والوں کی حالتِ باطنی جن احوال سے رنگین رہتی ہے، اسی جانب اشارہ حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ:
’’میرا حشر فرعون و ہامان و قارون کے ساتھ ہو، اور مجھے وہی عذاب پکڑے جس نے ان کو پکڑا تھا، اگر میرے دل میں یہ خطرہ بھی آئے کہ میں اس جماعت کا شیخ ہوں، یا ان کا سردار ہوں، یا مجھے اس بات کا وسوسہ بھی آئے کہ میں ان ہی میں سے ایک درویش ہوں، بھلا ان باتوں کی طرف اس شخص کا نفس کیونکر بلا سکتا ہے جو لاشئے ہے، (کچھ نہیں) کسی کام کے قابل نہیں، کسی گنتی اور شمار میں نہیں۔‘‘
حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ کی بندے سے محبت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت اپنے عیوب کا استحضار اور اپنی کم حیثیتی پر نگاہ ہونا بیان فرمایا ہے، جیسا کہ رقم طراز ہیں کہ:
’’ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتے ہیں، اُس کو وہ عیوب دکھلا دیتے ہیں جو خود اس کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دل میں تمام مخلوقات کی محبت و شفقت پیدا کردیتے ہیں، اس کے ہاتھ کو سخاوت کا عادی بنا دیتے ہیں اور اس کے نفس میں بلند ہمتی (اور چشم پوشی) پیدا کردیتے ہیں اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کو سب سے کم دیکھنے لگے اور کسی قابل نہ سمجھے۔ ‘‘
سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طریقِ اعترافِ خطا و قصور یا طریقِ ذلت و انکسار ہی کو حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب، روشن اور محبوب راستہ سمجھا اور سمجھایا ہے، جیسا کہ فرمایا :
’’ (دوستو!) میں نے اپنی جان کھپادی اور کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو طے نہ کیا ہو، اور صدقِ نیت اور مجاہدہ کی برکت سے اس کا صحیح (راستہ) ہونا معلوم نہ کرلیا ہو، مگر سنتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے، اور ذلت و انکسار والوں کے اخلاق پر چلنے، اور سراپا حیرت و احتیاج بننے سے زیادہ کسی راستہ کو بہت قریب اور زیادہ روشن اور (اللہ تعالیٰ کے نزدیک) زیادہ محبوب نہیں پایا۔
صدیقِ اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ عاجزی کے سوا کچھ نہیں بنایا (کیونکہ عاجزی تو ہر شخص آسانی سے حاصل کرسکتا ہے، انسان تو سر سے پیر تک عاجز ہی ہے، اگر اور کوئی طریقہ اللہ تک پہنچنے کا اس کے سوا ہوتا تو مشکل پڑجاتی، اللہ تعالیٰ کے پانے سے اپنی عاجزی (اور کمزوری) کو سمجھ لینا ہی اللہ تعالیٰ کا پالینا ہے۔
بزرگو! میں نے کوئی مشکل راستہ اور سہل طریقہ نہیں چھوڑا جس کے پردے نہ کھولے ہوں اور لشکرِ ہمت کے ہاتھوں سے اس کے بادبان نہ اُٹھا دیے ہوں، میں نے ہر دروازہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہا، مگر ہر دروازہ پر بہت زیادہ ہجوم پایا، تو میں ذلت و انکسار کے دروازہ سے پہنچا، اس کو میں نے خالی پایا، اور اسی سے واصل ہوکر اپنے مطلوب کو پالیا، دوسرے طالب (ابھی تک) دروازوں ہی پر کھڑے تھے، (کسی کو دربار تک رسائی نصیب نہ ہوئی تھی) مجھے میرے پروردگار نے اپنے فضل و عطاء سے وہ دیا، جس کو اس زمانہ میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔‘‘
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نسبتوں کی کئی ایک قسمیں ’’ہمعات‘‘میں لکھی ہیں، جیسے نسبتِ طہارت، نسبتِ عشق اور نسبتِ سکینہ، وغیرہ۔ ان نسبتوں کے متعلق یہ فرمایا کہ: یہ نسبتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک نسبت کے حصول سے اس کے ضمن میں ہی دوسری نسبتیں بھی اس میں بیدار ہوجاتی ہیں۔
راقم آثم کے نزدیک اس نسبت کا نام ’’نسبتِ اعترافِ قصور‘‘ رکھ لیں، ’’نسبتِ عبدیت‘‘ کہہ لیں، عنوان چاہے کسی قدر مختلف ہوں، معنون ایک ہی ہے۔ بقول شخصے:
عِبَارَاتُنَا شَتّٰی وَ حُسْنُکَ وَاحِدٌ
وَ کُلٌّ إِلٰی ذَاکَ الْجَمَالِ یُشِیْرٗ
اس نسبت کے حصول سے باقی ساری نسبتیں اس کے ضمن میں حاصل ہو جائیں گی، اگرچہ غلبہ کسی ایک نسبت کو ہو !
1- ایسے آدمی سے کبھی دعویٰ نہیں سنا جاتا اور اگر کبھی کسی پوشیدہ حالت کا اظہار ہوجائے یا دعویٰ منہ سے نکل جائے تو خلوت میں فوراً مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیوں میں مشغول ہوجاتا ہے۔
2- بعض صوفیاء سے جیسے کرامات کا صدور ہوتا ہے اور کثرتِ خلق کو برکات کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایسے شخص کو برکت تو درکنار اپنی نحوست کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ دل کبھی بھی اپنی کسی برکت، کرامت کے متعلق بات پر یقین نہیں کرتا اور اس کی وجہ کفرانِ نعمت نہیں، بلکہ اس حالت کا غلبہ ہے۔
3- ایسے اشخاص حق تعالیٰ سے دعاؤں میں اپنی بداعمالیوں کی نحوست سے مخلوقِ خدا کو بچائے رکھنے کی التجاؤں میں مشغول رہتے ہیں اور یہ اُن کی عارضی حالت نہیں، بلکہ مستقل حالت رہتی ہے۔
4- اگر ان کے کسی متعلق پر کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے تو یہ اسے صرف اور صرف اپنے اعمال کی نحوست کا شاخسانہ خیال ہی نہیں بلکہ یقین کیے ہوتے ہیں اور کوئی شے انہیں اس بات سے ہٹا نہیں پاتی، کیونکہ یہ ان کا مستقل حال ہے۔
5- اگر اَنفُس یا آفاق میں کوئی بھی اختلال یا انتشار برپا ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیاسی، معاشی، عائلی کسی بھی طرح کے حالات کی خرابی کو اپنے اعمال کی نحوست پر ہی محمول کرتے ہیں۔
6- انہیں کبھی کسی بھی شخص سے معافی مانگتے ہوئے عار نہیں آتی، یہاں تک کہ اپنے چھوٹوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی معافی مانگتے ہوئے کوئی مصلحت ان کے درپیش نہیں ہوتی، بلکہ اس حال کا رسوخ انہیں ایسی مصلحتوں کی طرف التفات نہیں کرنے دیتا، یا اگر کبھی کوئی مصلحت ان کی توجہ اپنی جانب کھینچتی بھی ہے تو ان کا یہ حال اس پر غالب آکر رہتا ہے۔
7- ایسے اشخاص سے اگر کوئی بیعت کی درخواست کرتا ہے تو یہ اسے جلد بیعت کرلیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے انہیں احتمالاً نہیں، بلکہ یقیناً برکات نصیب ہوں گی اور روزِ محشر معافی مل جائے گی۔
8- یہ عالمِ مکاشفہ میں اور خوابوں میں زیادہ تر اپنے آپ کو بری حالت میں ہی دیکھتے ہیں، کبھی انہیں حشر میں اپنا آپ جیسے انہیں گھسیٹ کر حق تعالیٰ کے سامنے مجرم کے طور پر لایا جارہا ہے، یہ مشاہدہ یا اس قسم کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔
9-انہیں عجب و کبر پیدا نہیں ہو پاتا، کیونکہ پندار جہاں سے پھوٹتا ہے، یہ اُسے جڑ سے اکھیڑ چکے ہوتے ہیں۔
10- حق تعالیٰ کی جانب سے ان کی تسلیوں کا خوب سامان کیا جاتا ہے، وگرنہ ان کا کلیجہ اپنے عیوب و ذنوب کے استحضار کے بوجھ سے پھٹ جائے۔ اتنے تسلی آمیز الہامات اور بشارتوں کے باوجود انہیں کبھی عجب پیدا نہیں ہوتا۔
11- یہ زیادہ تر قدمِ ابراہیم علیہ السلام پر ہوتے ہیں۔
12- اگر کوئی شخص ان پر کوئی احسان کرتا ہے تو حق تعالیٰ کے سامنے ان کا گریہ و بکا اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی حالت کو بدترین خیال کررہے ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کے احسان کے خود کو لائق نہیں سمجھتے۔
13- ان کی پہچان اس لیے بھی مشکل ہے کہ ان کے باطنی اعمال ظاہری اعمال سے زیادہ ہوتے ہیں۔
14- ان میں سے زیادہ کی غالب حالت یہ رہتی ہے کہ گریہ و بکاء کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور حق تعالیٰ کے سامنے خلوتوں میں خوب تڑپتے روتے ہیں۔
15- ان کا حضور مع اللہ کامل ہوتا ہے۔
16- حق تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا انہیں کامل استحضار رہتا ہے، جن نعمتوں کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں جاتی، انہیں ان کا بھی استحضار رہتا ہے۔
17- یہ کبھی کسی کے لیے بددعا نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی نہیں، اگرچہ ان کی باطنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کبھی اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ضرور پورا کریں، لیکن انہیں کبھی بھی اپنی حالت پر بھروسا نہیں ہوتا۔
18- حقیقتِ ’’رَضِیْتُ بِاللہِ رَبًّا‘‘ ان پر روشن ہوجاتی ہے۔ کسی بھی غم، دکھ، تکلیف یا عذاب میں انہیں جیسے ہی حق تعالیٰ کی یاد آتی ہے، دھیان آتا ہے، غموں، دکھوں، عذابوں سے تمتمایا ہوا دل یکلخت خنک ہوجاتا ہے۔ ایک ایسا Soothing Effect نصیب ہوتا ہے جسے بیان کرنے کے لیے، جس کی تعبیر کے لیے الفاظ کا سہارا بے کار ہے!
اس نسبت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
1- بتکلف، بہ جبر اور زور زبردستی سے ہی سہی، ہر نماز کے بعد دعا میں حق تعالیٰ کے سامنے خوب روئے اپنی خطاؤں پر اور اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بنائے رکھے، تاکہ ظاہر کا اثر باطن پر ہو اور دل کی زمین نرم ہوکر حق تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو خوب جذب کرلے۔
2- اَنفُس و آفاق میں، قومی، ملکی، عالمی سطح پر جس بھی طرح کے حالات کی اَبتری کا علم ہو، فوراً دل ہی دل میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا معترف ہوکر خوب معافیاں مانگے اور جبر سے خود کو یہ باور کرائے کہ میرے وجود کی ناپاکی ہی ہر خرابی کی وجہ ہے۔
3- حق تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگتا رہے کہ میری بدعملیوں کی نحوستوں سے میرے متعلقین، گھر والوں اور دوست احباب کو بچائے رکھیں۔
4- اپنے بھائیوں کے لیے غیب میں خوب حق تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔
5- سورۂ فاتحہ سے خاص تعلق پیدا کرے، کیونکہ اسی دروازے سے قرآن کریم میں داخلہ ہوتا ہے۔ ساری فتوحاتِ قرآنیہ، سورۂ فاتحہ ہی سے ممکن ہوتی ہیں۔
ہر نماز میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ’’اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ‘‘ پر خوب معنی کے استحضار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آگے بڑھے اور ہر اگلی آیت کے معنی کو خوب گہرا کرکے قلب میں سے اور اپنے پورے وجود میں سے گزارتا ہوا آگے بڑھتا رہے۔
6- اگر دل میں کبھی کسی سے کوئی رنج پہنچنے کی وجہ سے تکدُّر یا وحشت یا نفرت کا اثر ہو، فوراً قلب سے ان اثرات کو کھرچیں، تاکہ وہ راسخ نہ ہو پائیں، وگرنہ یہ ایسا قوی مانع ہے کہ اس نسبت کو راسخ نہیں ہونے دے گا۔