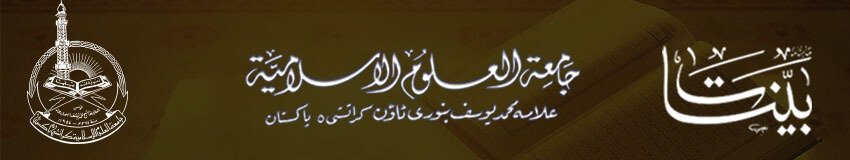
اصل موضوع شروع کرنے سے قبل بطور تمہید چند باتیں ملحوظ رہیں:
1- اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حدیثی یا تاریخی روایات وغیرہ کی صحت وضعف معلوم کرنے اور انہیں پرکھنے کے لیے ’’سند‘‘ کو بہت اہمیت حاصل ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ کا قول ہے: ’’الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء‘‘ (۱) یعنی ’’اسناد دین میں سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص جو چاہتا دینی باتیں بناکر کہہ دیتا۔‘‘ لہٰذا جس طرح کسی حدیث کا حکم معلوم کرنے کے لیے سند کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور محدثین کے بیان کردہ اصول وضوابط کے مطابق اس کے روات کو پرکھا جاتا ہے، اسی طرح تاریخی روایت کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں بھی سند کو مدِ نظر رکھا جائے گا۔
2- حضرات محدثین رحمہم اللہ احادیث جمع کرتے وقت اِسناد سے قطع نظر نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں تک ہوسکے اعلیٰ اور عمدہ سند ذکر کریں، جبکہ مؤرخین کے مدّنظر عام طور پر تاریخی روایات کو جمع کرنا تھا، خواہ سند یا متن کے اعتبار سے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، جیساکہ علامہ طبریؒ کی مندرجہ ذیل عبارت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے:
’’فما يکن في کتابي ہٰذا من خبر ذکرناہ عن بعض الماضين مما يستنکرہ قارئہ أو يستشنعہ سامعہ من أجل أنہ لم يعرف لہ وجہًا في الصحۃ ولا معنی في الحقيقۃ، فليعلم أنہ لم يؤت في ذلک من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليہ إلينا، وأنا إنما أدّينا ذٰلک علی نحو ما أدي إلينا۔‘‘ (۲)
یعنی ’’جو خبر ہم نے اس کتاب میں گزشتہ لوگوں کے بارے میں لکھی ہے، جسے پڑھنے والا عجیب جانے، یا سننے والا ناپسند کرے؛ کیونکہ اس کو اس خبر کا صحیح مفہوم یا حقیقی معنی معلوم نہ ہوسکا تو واضح رہے کہ اس میں کوئی بات اپنی جانب سے نہیں لائی گئی، بلکہ یہ نقل کرنے والوں میں سے کسی کی طرف سے آئی ہے، ہم نے اس خبر کو اسی طرح پہنچایا ہے جس طرح اس نے ہم تک پہنچائی۔‘‘
معلوم ہوا کہ احادیث مبارکہ کی طرح تاریخی روایات جمع کرتے وقت ان کی اِسنادی حیثیت پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی، لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ تاریخی روایات پر عمل کرنے کے لیے اسناد اور رواۃ سے اسی طرح بحث کی جائے گی جس طرح احادیث کے سلسلے میں بحث کی جاتی ہے، اور تاریخی روایات پرکھنے کے لیے بھی علم جرح وتعدیل پر عمل کیا جائے گا تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا، جیساکہ مشہور محقق علامہ معلمی یمانی ؒ فرماتے ہیں:
’’علی أن حاجۃ التاريخ إلی معرفۃ أحوال ناقلي الوقائع التاريخيۃ أشدّ من حاجۃ الحديث إلی ذٰلک، فإن الکذب والتساہل في التاريخ أکثر۔‘‘ (۳)
یعنی ’’تاریخی واقعات نقل کرنے والوں کے احوال جاننے کی طرف تاریخ کی ضرورت اور حاجت زیادہ ہے بنسبت حدیث کے ؛ کیونکہ جھوٹ اور تساہل تاریخ میں زیادہ ہے۔‘‘
مذکورہ تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ تاریخی روایات جانچنے کے سلسلے میں علم جرح وتعدیل کی اہمیت مسلّم وقابلِ قبول ہونے کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کسی تاریخی واقعہ کی صحت پرکھنے کے لیے علم جرح وتعدیل کے وہی اصول جاری نہیں کیے جائیں گے، جن سے کسی حدیث کی صحت اور ضعف کو پرکھا جاتا ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ تاریخی روایت کس قسم کی ہے، اگر وہ عقائد، احکامِ شرعیہ یا کسی معزز شخص پر طعن وتنقید وغیرہ پر مشتمل نہ ہو تو اس صورت میں ایسی تاریخی روایات پرکھنے میں زیادہ شدت اور سختی نہیں کی جائے گی، جس کی وجوہات اور دلائل حسبِ ذیل ہیں:
اولاً: بخاری شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے:
’’وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج۔‘‘ (۴)
ترجمہ: ’’بنی اسرائیل سے روایت بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔‘‘
اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بنی اسرائیل سے روایات بیان کی جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ روایت ان افراد کو شامل ہے جو اہل کتاب ہیں اور مشرف بہ اسلام نہیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ واقعات اور تاریخی باتیں وغیرہ بیان کرنے والا مسلمان نہ ہو، تب بھی اس کی باتیں دوسروں کو بیان کی جاسکتی ہیں، برخلاف احادیث کے، کیونکہ احادیث قبول کرنے کے سلسلے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی مسلمان ہو۔ نیز اہلِ کتاب وغیرہ سے ایسی باتیں اور روایتیں ہی لے سکتے ہیں جن کا تعلق عقائد واحکام وغیرہ سے نہ ہو، چنانچہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ صنعانی ؒ تحریر فرماتے ہیں:
’’(وحدّثوا عن بني إسرائيل) أي أرووا عنہم ما وقع لہم من الأعاجيب وإن استحال مثلہا في ہٰذہ الأمۃ کنزول النار من السماء لأکل القربان ولو کان بغير سند، لبعد الزمان، بخلاف الأحاديث المحمديۃ۔‘‘ (۵)
یعنی ’’ان سے ایسی عجیب باتیں روایت کرو جو ان کو پیش آئی تھی، اگرچہ اس امت میں اس جیسے واقعات بظاہر محال ہوں، مثلاً: قربانی کھانے کے لیے آسمان سے آگ کا اُترنا، طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے اگرچہ بغیر سند کے ہی کیوں نہ ہو، برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے۔‘‘
اور علامہ مناویؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:
’’(حدّثوا عن بني إسرائيل) أي بلّغوا عنہم القصص والمواعظ ونحو ذٰلک (ولا حرج) عليکم في التحديث عنہم ولو بلا سند۔‘‘ (۶)
یعنی ’’بنی اسرائیل سے قصے اور وعظ ونصیحت سے متعلق باتیں بیان کرو، اور ان سے روایات بیان کرنے کے سلسلے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اگرچہ بغیر سند کے ہو۔‘‘
اس حدیث پر اعتراض ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ بنی اسرائیل سے روایات لینا اور انہیں آگے بیان کرنا درست ہے، جبکہ بعض احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے روایت لینا یا ان کی دینی کتابیں پڑھنا ممنوع ہے، تو اس کے جواب میں علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کے درمیاں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ:
’’أراد ہنا التحديث بقصصہم نحو قتل أنفسہم لتوبتہم وبالنہي العمل بالأحکام۔‘‘ (۷)
یعنی ’’اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے قصے وغیرہ بیان کرنا، جیسے توبہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قتل کرنا، اور ممانعت سے مراد یہ ہے کہ ان کے احکام پر عمل کرنا۔‘‘
اور شاہ عبد الحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:
’’أشار إلی أن المراد التحدّث بالقصص والمواعظ والحکم والأمثال دون الشرائع والأحکام لنسخہا ووقوع التحريف فيہا۔‘‘ (۸)
اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے قصے، وعظ ونصیحت اور حکمت وغیرہ سے متعلق باتیں بیان کی جائیں، نہ کہ شرعی احکام سے متعلق روایات، کیونکہ وہ منسوخ ہیں، اور ان میں تحریف واقع ہوچکی ہے۔
اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ تاریخی روایات پرکھنے کے سلسلے میں علم جرح وتعدیل پر اس طرح عمل نہیں کیا جائے گا، جس طرح احادیث کی صحت وضعف معلوم کرنے کے لیے ان کی اسناد ورُوات کو پرکھا جاتا ہے، بلکہ جو تاریخی روایت کسی عقیدہ یا شرعی حکم وغیرہ سے متعلق نہ ہو، اس میں نقدِ سند کے سلسلے میں زیادہ شدت نہیں کی جائے گی۔
ثانیاً: حضرات محدثین رحمہم اللہ نے تصریح کی ہے کہ احادیث کا درجہ معلوم کرنے کے سلسلے میں بھی علمِ جرح وتعدیل کے اصول کا یکساں طور پر لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جو احادیث عقائد وفقہی احکام وغیرہ سے متعلق ہوں، ان میں دقتِ نظر اور سختی سے ان اصول کی رعایت کی جائےگی، اور جن احادیث کا تعلق فضائل ومناقب وغیرہ سے ہو، ان میں تساہل کا معاملہ ہوگا، جیساکہ امام احمد بن حنبلؒ کا قول ہے:
’’إذا روينا عن رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحکام تشدّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلی اللہ عليہ وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حکمًا ولا يرفعہٗ تساہلنا في الأسانيد۔‘‘ (۹)
ترجمہ: ’’جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایت بیان کرتے ہیں جو حلال وحرام یا سنن واحکامِ شرعیہ سے متعلق ہو تو ہم اسناد میں سختی کرتے ہیں، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی روایت بیان کرتے ہیں جو فضائلِ اعمال سے متعلق ہے، اور کسی حکم کو منسوخ وغیرہ نہیں کرتی تو ہم نقدِ اسناد میں چشم پوشی کرتے ہیں۔‘‘
اور مشہور محدث عبد الرحمٰن بن مہدیؒ فرماتے ہیں:
’’إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال، تساہلنا في الأسانيد والرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحکام تشدّدنا في الرجال۔‘‘ (۱۰)
یعنی ’’جب ہم ثواب وعقاب اور فضائلِ اعمال کے بارے میں حدیث روایت کرتے تو اسناد اور روات پرکھنے میں تساہل سے کام لیتے، اور جب حلال وحرام اور احکامِ شرعیہ سے متعلق حدیث روایت کرتے، نقدِ رُوات میں سختی سے کام لیتے۔‘‘
لہٰذا جب فضائل وغیرہ سے متعلق احادیث کے سلسلے میں اصولِ جرح وتعدیل پر سختی سے عمل نہیں کیا جاتا، اور ایسی روایات پرکھنے اور قبول کرنے کے سلسلے میں حضرات محدثین تساہل ونرمی کا کہہ رہے ہیں تو ایسی تاریخی روایات جو عقائد وفقہی احکام وغیرہ سے متعلق نہیں، ان میں بطریقِ اولیٰ تساہل سے کام لیا جائے گا، اور نقدِ اسناد میں زیادہ سختی نہیں کی جائے گی۔
ثالثاً: حضرات محدثین رحمہم اللہ نے متعدد راویوں کے بارے میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ ان کی بیان کردہ حدیث قابلِ قبول نہیں ہوگی، البتہ ان کی ذکر کردہ تاریخی روایات معتبر ہوں، یعنی روایتِ حدیث میں تو جرح کرکے ان کو ساقط الاعتبار کہا جاتا ہے، لیکن روایتِ تاریخ میں انہیں معتبر وقابلِ احتجاج قرار دیتے ہیں، چنانچہ حدیث وتاریخ کے ایک راوی سیف بن عمر تمیمی کے بارے میں علامہ ابن حجرؒ تحریر فرماتے ہیں:
’’سيف ابن عمر التميمي ۔ ۔ ۔ ضعيف [في] الحديث، عمدۃ في التاريخ۔‘‘ (۱۱)
یعنی’’ سیف بن عمر تمیمی حدیث میں ضعیف ہے، اور تاریخ میں قابلِ اعتماد ہے۔‘‘
اسی طرح تاریخ کے مشہور راوی ’’واقدی‘‘ کے بارے میں علامہ ذہبیؒ لکھتے ہیں:
’’وقد تقرّر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليہ في الغزوات والتاريخ، ۔ ۔ ۔ أما في الفرائض، فلا ينبغي أن يذکر۔‘‘ (۱۲)
ترجمہ: ’’یہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ واقدی ضعیف ہے، غزوات اور تاریخ میں وہ قابلِ احتجاج ہوگا ۔۔۔۔۔۔ فرائض واحکام کی احادیث میں اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں۔‘‘
اس سے معلوم ہوا کہ ایک راوی حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے ضعیف ہوگا، لیکن تاریخی روایات میں معتبر وقوی ہوگا، تو واضح ہوا کہ تاریخی روایات پرکھنے کے لیے ان کے راویوں پر بعینہٖ وہی اصول وضوابط جاری نہیں ہوں گے، جو احادیث کی صحت وضعف جاننے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
رابعاً: اہلِ علم کی ایک جماعت نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ تاریخی روایات پر نقد کرنے اور ان کی اسنادی حیثیت وغیرہ جانچنے کے سلسلے میں نرمی اور کچھ تساہل سے کام لیا جائے گا، زیادہ شدت اختیار نہیں کی جائے گی، جبکہ ایسی تاریخی روایات سے کوئی عقیدہ یا فقہی حکم بھی ثابت نہیں ہوتا، چنانچہ علامہ کافیجی ؒ (ت: ۸۷۹) فرماتے ہیں:
’’فإن قلت: فہل يجوز لہٗ أن يروي في تاريخہ قولاً ضعيفاً؟ قلت: نعم، يجوز لہٗ ذٰلک في باب الترغيب والترہيب والاعتبار مع التنبيہ علی ضعفہٖ، لکن لا يجوز ذٰلک في ذات البارئ عزّ وجل وفي صفاتہ، ولا في الأحکام۔‘‘ (۱۳)
ترجمہ: ’’اگر تم دریافت کرو کہ کیا تاریخ میں ضعیف قول روایت کرنا جائز ہے؟ تو میں جواب دوں گا کہ ہاں! ترغیب وترہیب یعنی اچھی باتوں کی طرف راغب کرنے اور برے امور سے ڈرانے وغیرہ سے متعلق جائز ہے، اس کے ضعف پر تنبیہ کرنے کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات یعنی عقائد اور احکام میں جائز نہیں۔‘‘
خلاصۂ کلام یہ ہے کہ ذکر کردہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ جو تاریخی روایات کسی عقیدہ یا شرعی حکم یا مسلماتِ دین وغیرہ سے متعلق نہ ہوں، انہیں جانچنے اور پرکھنے کے لیے علم جرح وتعدیل پر اس طرح عمل نہیں کیا جائے گا، جس طرح احادیث کی صحت وضعف معلوم کرنے کے لیے ان کی اسناد ورُواۃ کو پرکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسی تاریخی روایات کے سلسلے میں بھی انہی اصولِ جرح وتعدیل کی رعایت رکھی جائے گی تو تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ناقابلِ اعتبار ہوگا، چنانچہ معروف مؤلف اکرم ضیاء عمری رقم طراز ہیں:
’’أما اشتراط الصحۃ الحديثيۃ في قبول الأخبار التاريخيۃ التي لا تمسّ العقيدۃ والشريعۃ ففيہ تعسّف کثير، والخطر الناجم عنہ کبير؛ لأن الروايات التاريخيۃ التي دوّنہا أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملۃ الأحاديث، بل تمّ التساہل فيہا، وإذا رفضنا منہجہم، فإن الحلقات الفارغۃ في تاريخنا ستشکل ہوّۃ سحيقۃ بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرۃ والضياع والتمزّق والانقطاع۔‘‘ (۱۴)
یعنی ’’جو تاریخی روایات عقائد وشرعی احکام سے متعلق نہیں، انہیں قبول کرنے کے سلسلے میں احادیث کی صحت والی شرط لگانے میں بہت تکلف ہے، اور اس سے پیدا ہونے والا خطرہ بہت بڑا ہے؛ کیونکہ ہمارے اسلاف نے جن تاریخی روایات کی تدوین کی ہے، ان میں احادیث کا سا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس میں تساہل اور نرمی برتی ہے، تو اگر ہم ان کے اسلوب ومنہج کو چھوڑ دیں گے تو ہماری تاریخ میں خالی حلقے اور جگہیں پیدا ہوں گی، جو ہم اور ہمارے ماضی میں ایسی صورت پیدا کریں گی، جس سے تاریخ میں حیرت، ضیاع اور انقطاع پیدا ہوگا۔‘‘
۱- صحيح مسلم، مقدمۃ (۱/۱۵)، دار إحياء التراث العربي- بيروت
۲- تاريخ الملوک والأمم للطبري، (۱/۱۳)، الناشر: دار الکتب العلميۃ- بيروت، ط: ۱۴۰۷ھ
۳- علم الرجال وأہميتہ للمعلمي، (ص:۹۱)، الناشر: دار الرايۃ- الرياض، ط: ۱۴۱۷ھ
۴- صحيح البخاري، باب ما ذکر عن بني إسرائيل، رقم: ۳۴۶۱، (۴/۱۷۰)، الناشر: دار طوق النجاۃ، ط:۱۴۲۲ھ
۵- التنوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعاني(۴/۵۶۰)، الناشر: مکتبۃ دار السلام- الرياض، ط: ۱۴۳۲ھ- ۲۰۱۱م
۶- التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي، (۱/۴۹۵)، الناشر: مکتبۃ الإمام الشافعي- الرياض، ط: ۱۴۰۸ھ- ۱۹۸۸م
۷- فيض القدير للمناوي، (۳/۲۷۰)، الناشر: دار الکتب العلميۃ- بيروت
۸- لمعات التنقيح في شرح مشکاۃ المصابيح للدہلوي، (۱/۵۲۰)، الناشر: دار النوادر- دمشق، ط: ۱۴۳۵ھ- ۲۰۱۴م
۹- الکفايۃ في علم الروايۃ للخطيب البغدادي، باب التشدد في أحاديث الأحکام، (ص: ۱۳۴)، الناشر: المکتبۃ العلميۃ- المدينۃ المنورۃ
۱۰- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، بحث: تجنب الروايۃ عن الضعفاء، (۲/۹۲)، الناشر: مکتبۃ المعارف- الرياض
۱۱- تقريب التہذيب لابن حجر، (ص: ۲۶۲)، رقم: ۲۷۲۴، الناشر: دار الرشيد- سوريا، ط: ۱۴۰۶ھ- ۱۹۸۶م
۱۲- سير أعلام البنلاء للذہبي، (۹/۴۶۹)، الناشر: مؤسسۃ الرسالۃ- بيروت، ط: ۱۴۰۵ھ- ۱۹۸۵م
۱۳- المختصر في علم التاريخ للکافيجي، (ص: ۷۱)، الناشر: عالم الکتب- بيروت، ط:۱۴۱۰ھ- ۱۹۹۰م
۱۴- دراسات تاريخيۃ لأکرم ضياء العمري، (ص:۲۷)، الناشر: إحياء التراث العلمي-المدينۃ المنورۃ، ط:۱۴۰۳ھ- ۱۹۸۳م